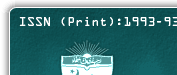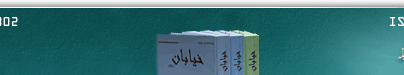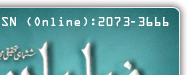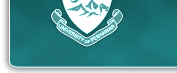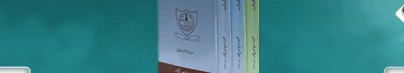اقبال اور اسپنگلر ایک تقابلی جائزہ
Abstract
The fall and rise of nations is an inevitable verdict of history. Iqbal and Spengler have made profound on this topic like other social scientists. Both thinkers have pointed out the essential ingredients which cause the fall and rise of nations and civilizations. Spengler is of the opinion that rebirth and renaissance of nations after their degeneration is not possible while Iqbal mentioned that this conception / idea could not be applied for the regeneration of Muslim Ummah. The Islamic renaissance is a glaring reality.
قوموں کے عروج و زوال، تہذیبوں کا ارتقا و انحطاط اور معاشرتی تغیر و تبدل تاریخ انسانی کا سنجیدہ موضوع ہے۔ جو ہر عہد میں اہل علم کی بحث کا عنوان رہا ہے۔ مسلمان مفکرین میں ابن خلدون، امام سخاوی، شکیب ارسلان، سید مودودی اور اقبال نے اس اہم موضوع پر عالمانہ اور مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے جب کہ مغربی مفکرین ٹائن بی، اسپنگلر، ویجوہیگل اور کارل مارکس نے اپنے اپنے انداز میں قوموں اور تہذیبوں کےعروج وزوال پر قابل قدر بحث کی ہے۔
ویجو (1648-1744) کے نزدیک بھی "قومیں مختلف مدارج یا منازل سے گزرتی ہیں۔ پہلا درجہ حیوانیت جس میں عقل و شعور جانوروں سے کچھ ہی بہتر ہوتا ہے دوسرا درجہ دیوتاؤں کا زمانہ ہوتا ہے جب قوم مافوق الفطرت عناصر یا دیوتاؤں کے خوف کے زیر اثر رہتی ہے۔ اس کے بعد "مشاہیر کا زمانہ" آتا ہے۔(1)
ویجوکے خیال میں اس مرحلے پرطبقاتی کشمکش شروع ھوتی ہے۔ اعلٰی اور ادنٰی کی یہ کشمکش بالآخر"عام لوگوں کا زمانہ" (2) یعنی فتح پرمنتج ھوتی ہے اس عروج کے زوال کا باعث، اخلاقی کمزوری، بددیانتی اور مذہب سے دوری ھوتی ہے (3) ویجوکے نزدیک آفاقی اصول ہے کہ"ہرپسماندہ قوم ترقی کرے گی اور ہرترقی یافتہ قوم کو زوال آئے گا"۔ (4)
ہیگل نے (1831ء) نظریہ جدلیت" پیش کیا اورThesis(عمل) Antithesis (ردعمل) Synthesis (اتحاد) کواپنے فلسفے کی بنیاد بنایا۔ کارل مارکس (1818۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔1883ء) نے ہیگل کے فلسفے کی مادی تعبیر کی اورجدلیاتی مادیت کا معروف نظریہ پیش کیا جس نے تاریخ پر بہت گہرے اثرات ثبت کیے۔
عمرانی مفکر ٹائن بی نے چیلنج اور مقابلہ (Challenge & Response) کا نظریہ پیش کیا اور شہرت دوام حاصل کی۔ اس طرح ابن خلدون (1332-1406ء) کے نزدیک "لوگوں کی طرح حکومتوں کی عمریں بھی طبعی ہوتی ہیں"۔(5) اور کوئی حکومت تین پشتوں سے زیادہ عمر نہیں پاتی۔ اب خلدون اس حوالے سے ایک سوبیس سال (6) کی مدت کا بھی تعین کرتے ہیں۔ اس مشہور عمرانی مفکر کی وفات کے پانچ سو سال بعد اوسوالڈ اسپنگلر (1880-1936ء) بھی قوموں اور تہذیبوں کو نامیاتی شے سے تعبیر کرتا ہے اور ان کی حیات کو بچپن، جوانی اور کہن سالگی سے تعبیر کرتا ہے اور فنا کے بعد دوبارہ عروج کو تسلیم نہیں کرتا۔
بیسویں صدی میں محکوم ہندوستان کے افق سی نمودار ہونے والا اقبال ان (ابن خلدون، اسپنگلر، ویجو) عمرانی مفکرین سے اختلاف کرتا ہے اور ساتویں صدی عیسوی میں تاریخ کے منظرنامے پرابھرنے اور پھر سترھویں صدی اس منظر نامے (امامت و قیادت) سے معزول ہونے والی امت مسلمہ کے دوبارہ عروج و مغربی تہذیب (جس کے فنا ہونے کی پیشن گوئی اسپنگلر نے بھی کی تھی) کی "خودکشی" کے بارے میں پرامید نظر آتا ہے۔
قوموں کے عروج و زوال کے ضمن میں اقبال کے افکار سمجھنے سے قبل اسپنگلر کے نظریات زیر بحث لانا ضروری ہیں۔
مشہور جرمن مفکر اسپنگلر جو ایک سادہ دیہاتی تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران و مابعد مشاہدات و تجربات حاصل کرتا ہےاوراپنےافکاروخیالات کو"زوال مغرب" Decline of Westمیں سمودیتا ہے اور دائمی شہرت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اسپنگلر کے مطابق تہذیبوں کا تسلسل ہی تاریخ ہےاورہرتہذیب (جس خاص قوم کی نمائندہ ہوتی ہے) انفرادی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔
تہذیبوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے لیکن تمام تہذیبوں میں عروج و زوال کا قانون ایک ہی ہوتا ہے اور آغازوانجام کےاعتبارسےتمام تہذیبیں ایک جیسے مدارج سے گزرتی ہیں جس طرح ایک جاندار کی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ اسپنگلر کے خیال میں "ہرثقافت کا بچپن، عنفوان شباب، جوانی اور پیرانہ سالی کا عہد ہوتا ہے۔ گویا ثقافت ایک انسان کی طرح اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتی ہے"۔(7) اس تاریخی حقیقت کا ادراک اسپنگلر نے کیا ہے کہ قوموں اور تہذیبوں کو دائمی عروج نصیب نہیں ہوتا بلکہ گردش ایام، نامی گرامی اقوام کو اوج ثریا سے زمین پر مار دیتی ہے۔ مغربی تہذیب جس کی ظاہری چمک دمک کے باعث اس کے زوال کے بظاہر تو کوئی آثار نظر نہیں آتے لیکن اسپنگلر کو مغربی تہذیب کا زوال نوشتہ دیوار لگتا ہے اس حوالے سے اسپنگلر کے چند اقوال ملاحظہ ہوں۔
"زوال مغرب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جوبیسویں صدی کے بعد آنے والے ہزاروں سالوں میں رونما ھوگا ہرمعقول شخص کو وہ ابھی سے آتا ھوا نظر آتا ہے۔" (8)
"ہروجودفانی ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ زبانیں، نسلیں، ثقافتیں سب عارضی ہیں۔ آج سے چند صدیاں بعدکسی مغربی ثقافت کا وجودنہیں ھوگا۔ کوئی جرمن، انگریزفرانسیسی نہ ھوگا۔" (9)
مغرب کے مستقبل سے متعلق رائے کا اظہارکرتے ھوئے اسپنگلرکہتاہے۔
"مغرب کا مستقبل غیرمحدودطورپرہمیشہ رفعت پذیرنہیں رہےگااوراس میں ہمیشہ موجودہ تصورات قائم نہیں رہیں گے۔ مگرتاریخ کاایک مظہرہے۔ جس کی ہیت اور مدت طے ھوچکی ہے۔ چند صدیاں اس کے نصیب میں ہیں جن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لوازمات طے کردہ شکل وصورت اور دستیاب نظیریں موجود ہیں۔ (10)" علامہ اقبال نے مادی تہذیب (مغربی تہذیب) کی خامیوں کوواضح کیاکہ
چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند
کرتے ہیں روح کو خوابیدہ، بدن کو بیدار(11)
اسپنگلر عظیم تہذیبوں کو پانی کی لہروں سے تشبیہ دیتا ہے گویا یہ تہذیبیں نقش برآب ہیں۔
"اس سطح زمین پر بھی عظیم ثقافتوں کے ادوار میں عظیم الشان لہروں کے بہاؤ کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ لہریں فوری طور پر بلند ہوتی ہیں۔ قطار اندر قطار آگے بڑھتی ہیں۔ اپنے جسم میں اضافہ کرتی ہیں اور غائب ہوجاتی ہیں اور پانی کی سطح پھر ایک بار پر سکون ہوجاتی ہے"۔ (12)
اسپنگلر تہذیبوں اور ثقافتوں کو نامیاتی شے سے تعبیر کرتا ہے کہ
"ہرنامیاتی شے کے لیے ولادت، موت اور فنا بقا بنیادی حیثیت کی حامل ہے"۔ (13)
تہذیبیں اپنی فطری عمر پوری کرتی ہیں اور فنا سے پہلے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی آخری کوشش کرتی ہیں۔
"تہذیب کی خاکستری صبح میں روح کے اندر جلتی ہوئی آتش ختم ہوجاتی ہے۔ ختم ہوتی ہوئی قوتیں آخری ہچکی کے لیے عارضی سراٹھاتی ہیں"۔ (14)
تہذیبوں کا زوال تدریجاًہوتا ہے اور زوال پذیر تہذیب موت سے قبل پھر سنبھلنے کے لیے انگڑائی لیتی ہے لیکن اس وقت قویٰ مضحمل ہوتے ہیں اور محض ماضی کی خوش کن یادیں اسے رومانیت کے جلو میں گہری نیندسلادیتی ہیں جو دائمی ہوتی ہے تو"روح ایک بار پھر فکرکا سہارا لیتی ہیں اور رومانیت میں پناہ لیتے ہوئے اپنے ایام طفولیت کی طرف ملتجیانہ نگاہ ڈالتی ہے۔ پھر آخر تھک ہارکر،اور زند گی کی حرارت سے محرومی کے زیراثر اپنی زندگی کی خواہش سے دست بردار ہوجاتی ہے۔جیسا کہ سلطنت روم کے ساتھ ہوا کہ خود ہی دن کی طویل روشنی میں اکتاکر ابتدائی تصوف کے اندھیروں میں پناہ لیتی ہے یعنی دوبارہ قبر کے مادری شکم میں غائب ہوجاتی ہے۔" (15)
ابن خلدون نے بھی حکومتوں کے مدارج بیان کیے ہیں اور تین پشتوں کی مدت بھی مقرر کی ہے اسپنگلر نے ابن خلدون سے پانچ سو سال کے بعد مدارج کےساتھ مدت کا تعین بھی کیا ہے کہ
"ہرثقافت کا بچپن، عنفوان شباب، جوانی اور پیرانہ سالی کا عہد ہوتا ہے۔" (16)
اسپنگلر نے تواتر سے لکھا ہے کہ
"ہر ثقافت کے اظہار ذات کے اپنے امکانات جو پیدا ہوتے ہیں، پکتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، گرجاتے ہیں مگر کبھی واپس نہیں آتے۔"(17) اسپنگلرتہذیبوں اور ثقافتوں کے دائمی فنا کا قطیعت کے ساتھ قائل ہے۔
"اس طرح پھول اور پھل ایک دوسرےسے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی بڑھوتری اور بہاراور خزاں کا عمل ہر ایک پر مختلف ہوتاہے اور رنگ وبو میں ہر طرح مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ثقافتیں بھی اپنی اپنی صفات کے اختلافات کے ساتھ وجود میں آتی ہیں جوان ہوتی ہیں۔ پھل پھول دے کر انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔" (18)
اسپنگلر نے ثقافت کو زیر بحث لاتے ہوئے کلاسیکل Classical Culture، مجوسی Magian Culture اور فاوستی Faustian Cultureمیں دنیا کی معلوم ثقافتوں کو تقسیم کیا ہے۔
کلاسیکل سے مراد قدیم یونانی اور ہندوستانی ہے جبکہ مجوسی میں یہودیت، عیسائیت، قدیم کلدانی مذہب، زرتشت اور اسلام کو شامل کیا ہے اور فاوستی سے مراد یورپی،مغربی تہذیب کو لیا جاتا ہے۔ اسپنگلر کے مطابق تو تہذیبیں اپنے خواص اور رویوں سے مختلف ہوتی ہیں فطری انداز سے زندگی کے مدارج طے کرتے ہوئے ان پر خزاں طاری ہوجاتی ہے اور یہ ہمیشہ پیوندخاک ہوجاتی ہیں۔
علامہ اقبال بھی قوموں اورتہذیبوں کے زوال کے منکر نہیں ہیں بلکہ وہ زوال کی تعبیر قدرت کے فطری اور اٹل قوانین کی روشنی میں کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اگر قومیں قیادت کے مطلوبہ اوصاف سے متصف ہوں تو انہیں عروج مل سکتا ہے۔ اقبال امت مسلمہ کے لیے دائمی فنا کے تصور کے خلاف ہیں البتہ جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا فطری امر ہے۔
مسلم تہذیب کے زوال میں دیگر تہذیبوں کا سا عمل نظر نہیں آتا یہاں زوال واحیا دونوں نظر آتے ہیں اسلامی تہذیب کی Disintegration نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی یہ Linear downfall ہے جس کی کوئی Bottom line نہیں۔
دیگر تہذیبوں کے مقابل، اسلامی تہذیب کی Bottom line تباہ نہیں ہوئی ہے اس کا سبب اس تہذیب کے اصل مآخذ قرآن و سنت کی مکمل حفاظت اور اصل صورت میں بحالی ہے جب کہ دیگر کسی بھی تہذیب کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے کہ اس کے مآخذ کی حفاظت کا ذمہ خود قادر مطلق نے لیا ہو۔
قرآن کے نزدیک تمہارے اندر ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا جو امت کو اس کے اساسی تصورات کی طرف لے جائے گا یہی احیاء کا سب سے معتبر ثبوت ہے۔
احیاء کی چار بنیادی جہتیں (Dimensions) ہیں:۔
۱۔ فکری احیاء Vision
۲۔ اخلاقی احیاء Moral
۳۔ منظم تبدیلی Institutional Change
۴۔ قوت Power
علامہ نے احیائے اسلام کی ان تمام جہتوں پر کام کیا ہے اور مغربی، مادی فلسفے کے ابطال کو ثابت کیا ہے۔ قدرت کا یہ قانون ایک حقیقت ہے کہ "وتلک الاایام ندوالھا بین الناس" یہ توزمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ (19)
مولانا ابوالکلام کے نزدیک "یہ گردش ایام قوموں اور ملتوں" جماعتوں اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ جاری و ساری رہا کرتی ہے۔ اس کی گرفت سے دنیا کا کوئی شاہ نہیں بچ سکتا۔ یہ اٹل اور لازوال حقیقت ہے۔(20)
جب کسی قوم کی صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر امامت اور قیادت ملتی ہےتو بلاوجہ اس مقام سے معزول نہیں کیا جاتا۔ فرمان الٰہی ہے:۔
وما کان ربک لیھلک القری بظلم و اھلھا مصلحون
"ایسا نہیں ہوسکتا کہ تیرا پروردگار قریوں کو بلاوجہ تباہ کردے حالانکہ اس کے باشندے صالح ہوں"۔ (21)
"صالح" کا مفہوم ابوالکلام آزاد نے اس طرح بیان کیا ہے۔ صلح کے معنی سنوارنے کے ہیں۔ فساد کے معنی بگڑنے اور بگاڑنے کے ہیں۔ صالح انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور دوسرے میں سنوارنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔
پس قانون یہ ہوا کہ زمین کی وراثت، سنورنے اور سنوارنے والوں کی وراثت میں آتی ہے۔ ان کی وراثت میں نہیں جو اعتقاد و عمل میں بگڑجاتی ہیں۔" (22)
اقبال نے اپنی فکر کو انہی قوانین کی روشنی میں جلا بخشی ہے اور صلاحیت اور اہلیت کے لیے فرد کی خودی اور امت کے لیے بے خودی کا تصور پیش کیا ہے۔ ابن خلدون نے بھی زوال کی علامت میں "عصبیت" کی کمزوری بتائی ہے۔ عصبیت سے مراد ابن خلدون وہ اعلیٰ جذبہ لیتا ہے جو کسی قوم یا گروہ کو باہم منظم رکھتا ہے۔ (23)
اسی طرح ابن خلدون "تعیش" کو بھی زوال کا سبب گردانتا ہے۔ علامہ اقبال اسپنگلر کے دائمی فنا کے فلسفے سے اختلاف کرتے ہیں اور عروج وزوال کو کچھ بنیادی اوصاف سے مشروط کرتے ہیں کہ اگر کوئی قوم ان اوصاف سے متصف ہو تو اسے دوبارہ عروج مل سکتا ہے۔ اقبال تن آسانی اور راحت پسندی کو زوال کا سبب بتاتے ہیں۔
میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے
شمشیروسناں اول، طاؤس ورباب آخر (24)
اقبال قوم کے جوانوں میں تن آسانی کو دیکھتے ہیں تو خون کے آنسوروتے ہیں۔
تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی
لہو مجھ کو رلاتی ہے جو انوں کی تن آسانی (25)
اقبال جدوجہد سے عاری زندگی کو بے کارتصور کرتے ہیں
ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے
بے معرکہ ہاتھ آئے جہاں تخت جسم و کے (26)
ڈاکٹرمحمدرفیع الدین کا تجزیہ برمحل ہے کہ جب قومیں روبہ زوال ہوتی ہیں تو
"نصب العین کی قوت اور شوکت روز بروز کم ہوتی جاتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے اور ان کے عمل کا جوش سرد ہونے لگتا ہے اور اس کے مداحوں اور عاشقوں کی محبت بھی اسی نسبت سے گھٹتی جاتی ہے وہ اپنی زندگی میں نصب العین کی محبت کے خلا کو پر کرنے کے لیے عیش و عشرت اور تماشا اور تفریح کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کی نسبت سے نصب العین کے ساتھ ان کی محبت کم ہوتی جاتی ہے اس نسبت سے عیش و عشرت کی طرف ان کی رغبت بڑھتی ہے اور یہ رغبت ان کی محبت کو اور کمزور کرتی جاتی ہے۔ عیش وعشرت سے قوم کی رغبت اس کے زوال کا سبب نہیں بلکہ اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہذا جب یہ صورت حال پیدا ہوجائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب قوم کا زوال اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے اور اس کی اجل قریب ہے۔ غلط نصب العینوں پر قائم ہونے والی نظریاتی جماعتوں کی تقدیر یہی ہے"۔ (27)
اپنے مضمون "قومی زندگی" (۱۹۰۴ء) میں اقبال تحریر کرتے ہیں۔
"میری نگاہ میں اس بڑھئی کے ہاتھ جو شیشے کے متواتر استعمال سے کھر درے ہوگئے ہیں ان نرم نرم ہاتھوں کی نسبت بدرجہا خوب صورت اور مفید ہیں جنہوں نے قلم کے سوا کسی اور چیز کا بوجھ کبھی محسوس نہیں کیا۔" (28)
شعری اسلوب میں بھی ایسا ہی اظہار ہے۔
زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ
جوئے شیر و تیشہ وسنگ گراں ہی زندگی (29)
غفلت میں پڑے انسانوں کے لیے اقبال کہتے ہیں
مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ
کہ جس کا شعلہ نہ ہو تندوسرکش و بےباک (30)
اقبال یہ اعلان کرتے ہیں
جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو (31)
علامہ کے کلام میں "خودی" کو بنیادی حثیت حاصل ہے۔ خودی کے مراحل کی تکمیل دراصل"عرفان ذات" ہےاورعرفان ذات ہی عرفان الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔جب فرد اس تصور سے عاری ہوگا تو پھر زوال اس کا مقدر ہے فرد،تن آسانی اور راحت پسندی کے بجائے سخت کوشی اور اجتماعیت کے لیےایثار اور قربانی اختیارکرتاہےتواجتماعی خودی(بےخودی)تشکیل پاتی ہے۔خودی اوربےخودی کایہی توازن مسلم معاشرےکی شیرازہ بندی ہے۔
سوزوگدازسےمعموریہ شعرجس میں اقبال بھی اپنےاپکوملامت کرتاہےکیسی درد کی کیفیت ہے۔
دیااقبال نےہندی مسمانوں کوسوزاپنا
یہ اک مردتن آسان تھا،تن آسانوں کےکام آیا (32)
اقبال لکھتے ہیں:
Character is the invisible force which determines the destination of the nations.(33)
یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادصبا گاہی
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی (34)
خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کراے غافل
یہی ہے اب تیرے لیے صلاح کارکی راہ (35)
فردروابط جماعت رحمت است
جوہر او راکمال ازملت است
ناتوانی با جماعت یارباش
رونق، ہنگامہ احرار باش (36)
فردمی گیردزملت احترام
ملت ازافرادمی یا بدنظام (37)
درجماعت فرد را بینیم ما
ازچمن اوراچوگل چینیم ما
فطرتش وارفتہ،یکتائی است
حفظ او را زانجمن ارائی است (38)
فرد کا نکتہ کمال اور عروج،ملت کے ساتھ وابستگی میں ہے۔
علامہ اقبال نے قوموں کےعروج زوال کی داستان میں فرد کی سیرت وکردار کی تعمیر کو اولیت دی ہے اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ فرد کے بغیر تعمیرمعاشرہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا۔ علامہ اقبال کے نزدیک "دنیا میں کسی قوم کی اصلاح نہیں ہوسکتی جب تک اس قوم کے افراد اپنی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ نہ دیں۔" (39)
فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں (40)
ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ (41)
اقبال کے نزدیک فرد کی جماعت سے علیحدگی دراصل اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین سے اکھڑ چکی ہوں اس لیے اسلامی تہذیب وتمدن کے ارتقااور عروج میں فرد اورجماعت کا تعلق بنیادی عامل ہے اور امت کے زوال کے اسباب میں یہی عامل کارفرما نظر آتا ہے اور دوبارہ عروج کے لیے بھی فرد (خودی) اور جماعت (بے خودی) میں ہم آہنگی بنیادی زینے ہوں گے۔
اسپنگلر تہذیبوں، ثقافتوں اور اقوام کو نامیاتی شے قرار دے کر دائمی فنا کی گھاٹیوں میں اتار دیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک فنا کا یہ قاعدہ امت مسلمہ پر لاگو نہیں آتا بلکہ نئے انقلابات، تغیرات اور حوادث زمانہ سے اسلامی تہذیب ازسرنو زندہ ہوتی ہے۔ البتہ اقبال بھی نوع انسانی کو جسم نامی ہی سے تعبیر کرتا ہے۔
“And we have created you all from one breath of life”. (42)
اقبال نے اسپنگلر کے کام پر اس طرح تبصرہ کیا ہے۔
"اب صرف اس غلط فہمی کا ازالہ باقی ہے جسے اسپنگلر نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "زوال مغرب" میں پھیلایا۔ اس تصنیف کے دو ابواب جس میں اس نے عربی ثقافت سے بحث کی ہے۔ ایشیا کی تہذیب وتمدن کی تاریخ میں ایک بڑا قابل قدر اضافہ تصور کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے۔ اسپنگلر نے ان دونوں ابواب میں یہ سمجھنے کی مطلق کوشش نہیں کی کہ بحیثیت ایک مذہبی تحریک اسلام کی ماہیت کیا ہے"۔ (43)
اقبال ایک حقیقت پسند مفکر تھے۔ انہوں نے اسپنگلر کو کلیتاً رد کیا اور نہ قبول کیا بلکہ اس کے بعض نظریات سے اختلاف کیا اور بعض سے اتفاق کیا۔ اسپنگلر کے خیال میں
European culture is through and through anticlassical. And this anticlassical spirit of European culture is entirely due to the specific genius of Europe, and not any inspiration she may have received from the culture of Islam, which according to Spengler, is thoroughly, Magian in spirit and character. (p.44)
اس نقطہ نظر سے دراصل اسپنگلر ان اثرات کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے جو مغربی تہذیب نے اسلام سے قبول کیے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں۔
I have however, tried to show in these lectures, that the anticlassical spirit of modern world has really arisen out of the revolt of Islam against Greek thought. It is obvious that such a view cannot be acceptable to Spengler, for if it is possible to show that the anticlassical spirit of modern culture is due to the inspiration which it received from the culture immediately preceding it, the whole argument of Spengler regarding the complete mutual independence of culture growths would callaps”. 45
اسپنگلر نے اسلام کو بھی مجوسی دائرے میں رکھ کر مطالعہ کیا ہے۔ اقبال نے اس پر اظہار کیا کہ "مجھے اس سے انکار نہیں کہ اسلام پر بھی مجوسیت کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یقیناً ان خطبات سے میرا مقصد یہ بھی ہے کہ میں اسلام کی روح کو اس اندازنگاہ سے محفوظ کروں اور اس پر سے مجوسیت کی چادراتار پھینکوں جس سے میری نظر میں اسپنگلر گمراہ ہوا۔(46)
تاتاری حملے کے نتیجے میں بظاہر امت مسلمہ نیست ونابود ہوئی۔ لیکن اس کے نتیجے میں "کعبے کونئے پاسبان" بھی مل گئے تھے۔
"جاوید نامہ" میں اقبال "سیر افلاک" کرتے ہوئے ذات اقدس سے مخاطب ہو کر عرض گزار ہیں کہ مردہ ہونے کے بعد قوم پھر کیسے اور کیونکر زندہ ہوسکتی ہے؟
چیست آئین جہانِ رنگ وبو جزکہ آب رفتہ نامی نایدبجو!
زندگانی راسرتکرار نیست فطرتِ او خوگرِتکرارنیست!
زیرگردوںرجعت اوناراواست چوںزپاافتادقومےبرنخاست!
ملتے چوں مرد،کم خیزوزقبر چارہ اوچیست غیرازقبروصبر! (47)
"ندائے جمال" سے جواب آتا ہے۔
چیست ملت اے کہ گوئی لاالہ؟ باہزاراں چشم بودن یک نگہ
اہل حق راجحت ودعویٰ یکےاست خیمہ ہائے ماجداد لہا یکے است!
زرہ ھا ازیک نگا ہی آفتاب یکہ نگہ شوتا شودحق بے حجاب!
ملتے چوں می شودتوحیدمست قوت وجبروت می آیدبدست!
روح ملت راوجودازانجمن روح ملت نیست محتاج بدن!
مردہ ازیک نگاہی زندہ شو بگذرازبے مرکزی پائندہ شو! (48)
اقبال نے قوموں کے عروج کے لیے "عشق اورفقر" کی خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ دونوں اوصاف خودی کی تعمیر میں ممدومعاون ہیں اور جس قوم کو فقر اور عشق کی دولت میسر آجائے اس کی تقدیر میں شکست نہیں ہوتی۔
خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم
عشق ہو جس کا جسور، قفر ہو جس کا غیور (49)
علامہ نے جس عہد میں آنکھ کھولی وہ مغربی غلبے اور استیلاء کا زمانہ تھا۔ مسلم معاشرہ تقدیر پرستی، جمود، تعصب، تنگ نظری اور فرقہ پرستی کا شکار تھا۔ اقبال نے امت کے مرض کی تشخیص کی اور ایک ماہر ڈاکڑ کی طرح ایک ایک مرض کا علاج تجویز کیا۔ امت مسلمہ کو یہ حوصلہ اور امید دلائی کہ مغربی تہذیب کا موجودہ غلبہ عارضی ہے اور غالب تہذیب جو بظاہر حسین اور پرکشش ہے اس کی حیثیت "شاخ نازک پر آشیانہ" سے زیادہ نہیں۔
دیار مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی دکان نہیں ہے
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرےگی
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا (50)
اپنے خطبات میں اقبال نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے۔
"یورپ میں عینی فلسفہ کو کبھی یہ درجہ حاصل نہیں ہوا کہ زندگی کا کوئی موثرجزوبن سکے اور اس لیے اب حالت یہ ہے کہ یورپ کی فساد زدہ خودی یا ھمد گراحریف جمہوریتوں کی شکل میں جن کا مقصد وحید ہی یہ ہے کہ دولتمندوں کی خاطر ناداروں کا حق چھینے اپنے تقاضے پورا کر رہی ہے۔ یقین کیجیے کہ یورپ سے بڑھ کر آج انسان کے اخلاقی ارتقا میں بڑی رکاوٹ اور کوئی نہیں"۔ (51)
یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے
حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان یہ ظلمات (52)
اور مسلمانوں کو یہ نکتہ سمجھایا کہ
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی (54)
اقبال نے قوموں کے عروج وزوال کی بحث میں عمرانی مفکرین ابن خلدان، اسپنگلر، ویجوسے اختلاف کیا اور مسلمانوں کے زوال اور محکومی کو ایک عارضی دور سمجھا اور اپنی ساری زندگی احیائے اسلام کے لیے وقف کی۔ خالصتاً عقلی اور منطقی استدلال سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا اور بے تاب جذبوں اور مضطرب آزووں کے ذریعے اپنے پیغام کو حیات آفریں بنادیا۔
بیسویں صدی کی تاریک فضا میں اقبال کی طرف سے احیائے اسلام کی یہ روشنی اور امید افزا نوید صور اسرافیل سے کم نہیں ہے۔
آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہوجائےگا
اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہوجائے گا
پھر دلوں کو یادآجائےگا پیغام سجود پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہوجائے گا
شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے (55)
جب کہ اسپنگلر اپنی مغربی تہذیب کے خاتمے کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ
"زوال مغرب جو بیسویں صدی کے بعد آنے والے ہزارسالوں میں رونما ہوگا۔ مگر ہر معقول شخص کو وہ ابھی سے آتا ہوا نظر آرہا ہے"۔ (56)
بیسویں صدی کا مشہور مورخ، آرنلڈ، ٹائن بی اپنی شہرہ آفاق تصنیف "مطالعہ تاریخ" (Study of History) میں لکھتا ہے۔
"ہم اس حقیقت سے دو چار ہیں کہ اکیس تہذیبوں میں سے جو زندہ پیدا ہوئیں اور انہوں نے نشووارتقا پایا تیرہ مرکردفن ہوچکی ہیں بقیہ آٹھ میں سے سات بدیہی طور پر معرض انحطاط میں ہیں آٹھویں جو ہماری اپنی تہذیب (مغربی تہذیب) ہے ممکن ہے نصف النہار سے گزر چکی ہے"۔ (57)
جب کہ علامہ اقبال اپنی ملت کی فنا اور معدوم ہونے کی پیشن گوئی کرنے کےبجائے یہ حیات آفریں پیغام دیتے یہں۔
عہد نو برق ہے آتشزن ہر خرمن ہے
ایمن اس سے کوئی صحرانہ کوئی گلشن ہے
اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے
ملت ختم الرسل شعلہ بہ پیراہن ہے
آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا
اقبال اور دیگر عمرانی مفکرین کا یہ اختلاف دراصل حیات و کائنات کے بارے میں تصورات اور نکتہ ہائے نظر میں اختلاف کا اظہار ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک "عالم انسانی کو آج تین چیزوں کی ضرورت ہے کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کی روحانی استخلاص اور وہ بنیادی اصول جن کی نوعیت عالمگیر ہو۔ اور جن سے انسانی معاشرے کا ارتقا روحانی اساس پر ہوتا رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اس میں کوئی شک نہیں جدید یورپ نے اس نہج پر متعدد عینی نظامات قائم کیے لیکن تجربہ کہتا ہے کہ جس حق و صداقت کا انکشاف عقل محض کی وساطت سے ہو اس سے ایمان ویقین میں وہ حرارت پیدا نہیں ہوتی جو وحی و تنزیل کی بدولت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عقل محض نے انسان کو بہت کم متاثر کیا ہے"۔(59)
جبکہ ٹائن بی، اسپنگلر، ویجو، کارل مارکس اور دوسرے عالی دماغ مفکرین حیات و کائنات کی گرہیں مادی تعبیر کے ذریعے کھولنے میں کوشاں رہے اور محض عقل کو آخری ذریعہ علم تصور کرتے رہے جبکہ اقبال کائنات کی ابتداء اور انتہاء اور اس کے اسرار و رموز الہامی کلام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وحی کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں اور عقل کو محض "چراغ راہ" تصور کرتے ہوئے انسان کی منزل دائرہ اطاعت الہی میں خیال کرتےہیں۔ اسی ایک نکتے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ محیر العقول انسانی ترقی اور انسانی ایجادات نے انسان کو خوف و خطرے میں مبتلا کردیا ہے اور انسانیت آج تباہی کے دھانے پر کھڑی اپنی ہی ایجادات کے ہاتھوں تباہی و ہلاکت کی منتظر ہے کہ
ع فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب (60)
حوالہ جات
۱۔ افتخار حسین آغا، ڈاکٹر، قوموں کی شکست و زوال کے اسباب کامطالعہ، مجلس ترقی ادب کلب روڈ لاہور، ۱۹۹۲ء، ص ۱۹۱
۲۔ ایضاً
۳۔ ایضاً
۴۔ ایضاً
۵۔ مقدمہ ابن خلدون، ص ۲۵۳
۶۔ ایضاً
۷۔ اسپنگلر،زوال مغرب حصہ اول، ص ۱۲۸، ترجمہ مظفر حسین ملک، ڈاکٹر (اسلام آباد مقتدرہ قومی زبان ۲۰۰۴ء)
۸۔ ایضاً
۹۔ ایضاً، ص ۱۸۲
۱۰۔ ایضاً
۱۱۔ کلیات اقبال، ضرب کلیم، ص ۷۶۳
۱۲۔ اسپنگلر، زوال مغرب، ص ۶۵
۱۳۔ ایضاً، ص ۲۸
۱۴۔ ایضاً، ص ۱۲۹
۱۵۔ ایضاً، ص ۱۲۹
۱۶۔ ایضاً، ص ۱۲۹
۱۷۔ ایضاً
۱۸۔ ایضاً
۱۹۔ القرآن پارہ نمبر۴، آل عمران، آیت نمبر ۱۴۰
۲۰۔ قرآن کا قانونِ عروج و زوال، ص ۱۰۸، (ابوالکلام آزاد، مولانا، لاہور مکتبہ جمال اردو بازار لاہور ۲۰۰۱ء)
۲۱۔ القرآن
۲۲۔ قرآن کا قانونِ عروج و زوال، ص ۱۰۰
۲۳۔ مقدمہ ابن خلدون، ص ۲۵۳
۲۴۔ محمد اقبال، کلیات اقبال اردو، بال جبریل، ص ۴۸۶ (شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، ۱۹۷۳ء)
۲۵۔ کلیات اقبال اردو، بال جبریل، ص ۵۷۰
۲۶۔ کلیات اقبال اردو، ضرب کلیم، ص ۷۶۱
۲۷۔ محمد رفیع الدین، ڈاکٹر، حکمت اقبال، ص ۱۸۱
۲۸۔ مقالات اقبال، ص۹۹، محمد اقبال، مرتب عبدالواحد سید، اقبال قریشی(لاہور،آئینہ ادب ۱۹۸۲ء)
۲۹۔ کلیات اقبال (اردو)، ص ۲۵۹
۳۰۔ ایضاً، ضرب کلیم، ص ۷۵۸
۳۱۔ کلیات اقبال (اردو)، ص ۲۵۹
۳۲۔ کلیات اقبال اردو، بال جبریل، ص ۵۵۹
۳۳۔ Stray Reflection P-79
۳۴۔ کلیات اقبال اردو، بال جبریل، ص ۲۷۱، (الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور ۱۹۹۵ء)
۳۵۔ ایضاً، بال جبریل،ص۲۷۲، (کلیات اقبال، الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور)
۳۶۔ کلیات اقبال فارسی، ص ۸۵
۳۷۔ ایضاً، ص ۸۶
۳۸۔ ایضاً، ص ۸۸
۳۹۔ مقالات اقبال، ص ۵۳
۴۰۔ کلیات اقبال اردو، ص ۲۶۷ (نظم شمع و شاعر)
۴۱۔ ایضاً، ص ۱۹۴، کلیات اقبال مرتبہ الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور
۴۲۔ Reconstruction of Religious thought in Islam. P-112 Lahore Iqbal Acd 1989
۴۳۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ص ۲۱۸، مترجم نذیر نیازی لاہور! بزم اقبال ۱۹۸۲ء
۴۴۔ Reconstruction of Religious thought in Islam. P-114 Lahore
۴۵۔ ایضاً
۴۶۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ص ۲۱۹، ۲۲۰
۴۷۔ کلیات اقبال(فارسی)، ص ۷۷۹، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور
۴۸۔ ایضاً، ص ۷۸۰، ۷۸۱
۴۹۔ کلیات اقبال (اردو)، ضرب کلیم، ص ۴۲۶ (الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور)
۵۰۔ کلیات اقبال اردو، ص ۱۰۵
۵۱۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ص۲۷۶
۵۲۔ کلیات اقبال اردو، ص ۳۳۲ (الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور)
۵۴۔ کلیات اقبال اردو، ص۱۹۰، ایضاً
۵۵۔ ایضاً، ص ۱۴۷
۵۶۔ زوال مغرب، جلد اول، ص ۱۲۸
۵۷۔ ٹائن بی، مطالعہ تاریخ، حصہ اول، ص ۴۹۶
۵۸۔ کلیات اقبال اردو، ص ۱۵۶ (جواب شکوہ)
۵۹۔ تشکیل جدید الہیات، ص ۲۷۵، ۲۷۶
۶۰۔ کلیات اقبال اردو، ص ۴۴۲ (الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور)
کتابیات
۱۔ آغا، افتخار حسین، ڈاکٹر، قوموں کی شکست و زوال کے اسباب کا مطالعہ، (لاہور!مجلس ترقی ادب، ۱۹۹۲ء)
۲۔ ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمہ(کراچی، نفیس اکیڈمی ۲۰۰۱ء)
۳۔ ابوالکلام آزاد، مولانا، قرآن کا قانونِ عروج وزوال، (لاہور،مکتبہ جمال اردو بازار (۲۰۰۱ء)
۴۔ اوسوالڈاسپنگلر، Decline of west، (زوال مغرب)مترجم مظفر حسین ملک، ڈاکٹر (اسلام آبادمقتدرہ قومی زبان ۲۰۰۴ء)
۵۔ ٹائن بی، آرنلڈ (Study of history) مطالعہ تاریخ، مترجم غلام رسول مہر، (لاہورمجلس ترقی ادب، ۱۹۵۷ء)
۶۔ قرآن مجید (لاہور تاج کمپنی لمیٹیڈ ۱۹۹۰ء)
۷۔ محمد اقبال، کلیات اقبال (اردو)، (الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور ۱۹۹۵ء)
۸۔ محمد اقبال، کلیات اقبال (اردو)، (لاہور! شیخ غلام علی اینڈ سنز ۱۹۷۳ء)
۹۔ محمد اقبال، کلیات اقبال (فارسی)، (لاہور! شیخ غلام علی اینڈ سنز ۱۹۷۳ء)
۱۰۔ محمد اقبال، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ (مترجم نذیر نیازی) (لاہور: بزم اقبال، ۱۹۸۶ء)
۱۱۔ محمد اقبال، مقالات اقبال، مرتب عبدالواحد، اقبال قریشی، (لاہور: آئینہ ادب ۱۹۸۲ء)
۱۲۔ محمد رفیع الدین، ڈاکٹر، (اسلام آباد: ادرہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ۱۹۹۲ء)
۱۳۔ Iqbal, the reconstruction of religious thought in Islam.
(Lahore! Iqbal Academy 1989)