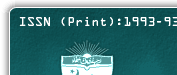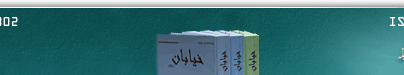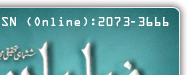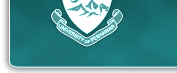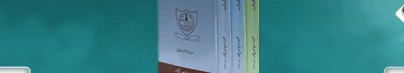بیسویں صدی کی آخر دو دہائیوں میں اُردو ناول کے موضوعات و رجحانات
Abstract
Urdu novel have critical importance in the Pakistani literature. All the major events took place in the socio-political history of Pakistan can be realized in this form of fiction. The last two decades were to significant to sect the behavior and the new trends of Urdu novel. In the 80’s the Marshal Law of General Zia-ul-Haq brought extremism in the society. The demolishing of democratic government in the last decade have deep impacts on the topics of Urdu novel. The effect of destruction of feudalism can also be seen in the trends of Urdu novel of this era.
اُردو ناول میں ارتقائی تبدیلیوں کی بڑی وجہ سماج میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی تغیرات ہیں۔ اگر ناول کی ابتداء سے بات کریں تو ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی برطانوی راج، بعد ازاں تحریک پاکستان کی جدو جہد، قیام پاکستان اور ایک خون آشام ہجرت ہے جو طویل عرصے تک ہمارے اُردو ناول کا موضوع رہی ہے۔ دراصل ناول میں زندگی کا مطالعہ ایک 'کل' کی صورت میں کیا جاتا ہے لہٰذا اس کل کی تشکیل کرنے والے جملہ تہذیبی، تاریخی، سماجی اور اقتصادی امور سے آگہی ضروری ہوجاتا ہے۔ خصوصاً جب ہم بیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں میں ناول کی صنف کا جائزہ لیتے ہیں تو کم و بیش پچاس، ساٹھ سال ماضی کے پس منظر کو اجاگر کرنا ضروری ہوجاتا ہے تب ہی ان دو دہائیوں کی معنویت اجاگر ہوتی ہے۔
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کا سیاسی ماحول کبھی بھی مستحکم نہیں رہا اور اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے کی طرح ادب پر بھی پڑے۔ یہ سیاسی ماحول آغاز سے ہی جس نہج پر استوار ہوا اس میں پاکستانیت، نظریہ پاکستان، مسلمان کے طرزِ احساس وغیرہ جیسے الفاظ کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ ایک سطح پر تو نہایت سنجیدہ مباحث ہوئے مگر دوسری طرف کچھ لوگوں پران لفظوں نے شہرت عام و بقائے دوام کے دربھی واکئے۔ مصلحت کے پس منظر میں یقیناً وہ تحفظ کا احساس چھپا ہوا تھا جو ان پر ادبی اور ثقافتی اداروں کی رکنیت کی چھاپ لگاتا تھا۔ میں احمد جاوید کے مضمون "پاکستانی ادب کی شناخت کے ان لفظوں کو شک کی نظر سے دیکھتی ہوں کہ:
"پاکستان چونکہ مارشلاوں کی زد میں رہا اس لئے ادب کی جمہوری اقدار کی ریاستی سطح پر تو خیر کیا پذیرائی ہونا تھی بعض دانشوروں کے ہاں بھی قبولیت کا درجہ حاصل نہ کرسکیں اور ایسا ادب بسا اوقات ریاستی نظریئے کی ضد قرار پایا جو عوامی امنگوں اور جمہوری قدروں کی پاسداری کرتا تھا۔"(۱)
اس میں صرف یہاں تک بات درست ہے کہ پاکستان اپنے قیام کے بعد سے مسلسل فوجی حکمرانوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ اختصار کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تفصیل کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں پہلا مارشل لاء ۱۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو نافذ کیا گیا یوں ایوب خان جو پاکستان کی بری افواج کے پہلے مسلمان اور پاکستانی کمانڈر انچیف تھے۔ بر سرِ اقتدار آگئے۔ یہ مارشل لاء ۸ جون ۱۹۶۲ء تک مسلط رہا۔ ۲۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو یحیٰی خان نے ملک میں دوسرا مارشل لاء نافذ کردیا جو تقریباً پونے تین سال مسلط رہا۔ یحیٰی خان نے ۱۹۷۰ء کے انتخابات کرائے تو ایک موقع ہاتھ آیا لیکن عوامی لیگ کی کامیابی کے بعد بھی جب اقتدار منتقل ہوتا نظر نہ آیا تو بنگالی مسلح جدوجہد پر اتر آئے جو بنگلہ دیش کے قیام پر ختم ہوئی۔ یوں یحیٰی خان کی فوج آمریت نے ملک کے دو ٹکڑے کردیئے۔ ذوالفقارعلی بھٹو نے ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء کو پاکستان کے صدر اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے۔ یہ صورتحال ۲۱ اپریل ۱۹۷۲ء تک رہی۔ جب ایک عبوری دستور نافذ کرکے مارشل لاء ہٹایا گیا۔ ۱۴ اگست ۱۹۷۳ء کو ملک کا تیسرا دستور نافذ ہوا تو بھٹو نے عہدہ صدارت چھوڑ کر وزارتِ عظمٰی کا عہدہ سنبھال لیا۔
۱۹۷۱ء سے پہلے کے دور میں جھانکیں تو نظر آتا ہے کہ ملک اپنی تاریخ کے مایوس ترین دور سے گزر رہا ہے۔ عوام مایوسیوں اور تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مشرقی پاکستان کا سانحہ اور فوجی شکست لوگوں کے دلوں کو کچوکے لگا رہی تھی۔ عوام اعتماد کھوچکے تھے۔ اور ان کے ذہنوں میں نئے خدشات اور مزید شکست وریخت کے خطرات اور اندیشے سر ابھار رہے تے۔ پاکستان فالج زدہ لگ رہا تھا۔ ملک کی معاشی و تجارتی حالت دگرگوں تھی۔ خزانہ خالی ہوچکا تھا۔ اسکے علاوہ اسی دوران پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور انڈین پروپیگنڈہ نے اسے تنہا اور بے دست وپاکر دیا جو ممالک ۱۹۶۵ء میں دوستی کا دم بھرتے تھے ۱۹۷۱ء کی جنگ میں تقریباً لاتعلق رہے۔ ہر شعبے میں بحران ہی بحران دکھائی دیتا تھا۔ دل شکستہ عوام مستقبل سے خائف تھے ابلاغِ عامہ کے عالمی ذرائع کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈہ پاکستانی عوام کے رہے سہے حوصلوں کو بھی پست کر رہا تھا۔ ایسے میں بھٹو کے پوری دنیا میں طوفانی دورے، ۱۹۷۴ء میں اسلامی سربراہی کانفرنس، اقوام متحدہ میں تیسری دنیا کے ملکوں کے لئے آواز بلند کرنا، بین الاقوامی اقتصادی نظام کی تشکیل کے لئے راہیں ہموار کرنا، پاکستان کو ایٹمی توانائی فراہم کرنے کی ان تھک اور کامیاب کوششوں کے خاطر خواہ نتائج سامنے آنا شروع ہی ہوئے تھے کہ ۱۹۷۷ء میں ایک مرتبہ پھر ملک آمریت کا شکار ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی باقاعدہ فوجی سروس کے دوران میں ریفرنڈم کے ذریعے عوامی توثیق حاصل کی۔ کس طرح؟ یہ الگ کہانی ہے۔ ۱۹۸۵ء میں آئینی ترمیم کے بعد جنرل ضیاءالحق کو سیاسی طور پو وسیع اختیارات حاصل ہوگئے۔ اس عرصے کے دوران فوج ان کی وفادار رہی اور یہ سلسلہ نجانے کب تک جاری رہتا کہ سانحہ بہاولپور وقوع پذیر ہوا اور جنرل ضیاءالحق مارے گئے۔
اس کے یکے بعد دیگرے، سیاسی حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہیں کہ ایک مرتبہ پھر ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۹ء میں جنرل پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو بن کر عوام کے سروں پر مسلط ہوگئے۔ انہوں نے بھی ریفرنڈم کے ذریعے اپنی صدارتی مدت میں توسیع کی اور کئی سال تک صدرِ پاکستان کے عہدے پر قابض رہے۔
جو ملک اتنے فوجی آمروں کے ہاتھ میں رہا ہو وہاں جمہوریت، معاشی اور سیاسی استحکام کس طرح پیدا ہوسکتا ہے۔ ہر حکمران نے حکومت سنبھالتے ہوئے سب سے پہلے خزانہ خالی ہونے کا رونا رویا ہے۔ بھٹو کے دور میں کچھ صنعتوں کو قومیانے سے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ علاوہ ازیں ملک کا ہر شعبہ متاثر ہوا۔ افغانستان سے مہاجرین نے پاکستان ہجرت کی جس سے ملکی معیشت بہت متاثر ہوئی۔ علاوہ ازیں ملک میں اسلحہ، کلاشنکوف کلچرمتعارف ہوا۔ سانحہ اوجڑی کیمپ پیش آیا۔ ضیاء الحق کے بعد بے نظیر، نواز شریف کی حکومتیں بنتی بگڑتی رہیں اور کوئی بھی جمہوریت پر مبنی نظام ملک میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوسکا۔ اس دوران کراچی کے سیاسی حالات ابتری کا شکار ہوئے اور ایم کیو ایم نے مہاجرین کے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی۔ کراچی جسے روشنیوں کا شہر اور عروس البلاد کہا جاتا ہے خون ریزی اور دہشت گردی کے اندھیروں میں ڈوب گیا اور پاکستان کا دارلحرب بن گیا۔ جنرل مشرف نے Take over سے قبل نواز شریف کے دور میں پاکستان اور انڈیا کی فوجیں ایک متربہ پھر کارگل میں ٹکرائیں۔ نواز شریف کو امریکہ طلب کیا گیا۔ واپسی پر نواز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف میں اختلاف بڑھا اور مشرف نے کچھ عرصہ بعد بساط الٹ دی اور یوں جمہوری حکومت اپنی مدت پوری کئے بغیر ناکام ہوگئی۔
مارشل لا کے اس پس منظر کا جائزہ لینے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ سیاسی طور پر کبھی بھی مستحکم نہیں رہا۔ مارشل لاء کے اثرات آہستہ آہستہ سرایت کرکے معاشرے کی اندرونی پرت تک پہنچ گئے۔ خوف اور بے سمتی کی فضا نے تخلیق کاروں کے ذہن کو متاثر کیا۔ دوسری شخصیت کی دریافت، باطنی شکست وریخت، مجمع یں تنہائی کا احساس نمایاں موضوع بن گئے۔ ۱۹۷۷ء کے مارشل لاء نے بالخصوص بے سمتی اور منافقانہ رویئے کو فروغ دیا۔ وہاں شدت پسندانہ روئے کو بھی پنپنے کا موقع دیا۔ گیارہ سالہ آمریت میں مزاحمت کا ایک نیا دور اور نیا لب و لہجہ وجود میں آیا۔ ضیاء دور کے بعد بارہ سالوں میں چار منتخب اسمبلیوں کی ٹوٹ پھوٹ سے جمہوری عمل کا اعتبار جاتا رہا۔ ایک مجموعی لا تعلقی نے بے حسی اور مایوسی کے رجحانات کو فروغ دیا اس کی چھاپ ادب کی سب ہی اصناف پر دکھائی دیتی ہے۔
خصوصاً ۱۹۸۰ء کے بعد شائع ہونے والے ناولوں میں ان اثرات کو واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ایک تو وہ رجحان جو ۱۹۸۰ء سے پہلے چلا آرہا تھا یعنی تقسیم سے پیدا شدہ حالات، ہجرت کا کرب، نئی زمین پر بسنے کا مسئلہ، مخصوص جاگیرداری نظام کی ٹوٹ پھوٹ اور دوسری طرف مغرب سے اخذ شدہ تصورات کی روشنی میں اپنے مسائل کو سماج کے حوالے سے بیان کرنا، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کو ناول میں جگہ دے کر اس کے دائرہ کر کو وسعت دینا ہے۔ اس لئے جہاں ہمیں ۱۹۸۰ء سے اُردو ناول میں ابھی تقسیم سے پیدا شدہ حالات، جاگیرداری نظام کی ٹوٹ پھوٹ اور مہاجرین کو نوسٹلجائی کیفیت کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ وہیں ناول میں کچھ نئے تجربات بھی سامنے آتے ہیں مثلاً انور سجاد کے ناول "خوشیوں کا باغ" (۱۹۸۱ء) کی صورت میں تمثیلی، استعاراتی اور تجریدی اسلوب کا حامل سیاسی، سماجی، قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا منظر نامہ پوش کی مصوری کے نقطہ نظر سے پیش کیا ہے۔ ناول کی کہانی سیدھے سادے انداز میں کہنے کے بجائے تصور کے پس منظر کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اس بیان میں اپنے عہد کے مسائل کو سمودیا گیا ہے لیکن انداز قدرے مختلف ہے۔ اسلوب ملاحظہ فرمائیے:
"تو کہاں ہے؟ ہم تیرا انتظار کرتے ہیں امام مہدی ہمارے جسموں کا پانی ختم ہوتا ہے۔
مسیح موعود ہمارے معدوں میں خلا ابھرتے ہیں،گوڈوہمیں ہماری کشتی تک لے جا بادبان کھول، رسیاں تھام تو آتا کیوں نہیں دن ڈوبتا کیوں نہیں سورج نکلتا کیوں نہیں۔" (۲)
امام مہدی، سمیح موعود اور گوڈویہ تینوں کردار جن کے عمل پر انقلاب کا دارمدار ہے۔ ناول میں پلاٹ کے درمیان بار بار ابھرتے ہیں۔
انور سجاد کا دوسرا ناول "جنم روپ" (۱۹۸۵ء) بھی بوش کی تصویر کے زیر اثر لکھا گیا ہے کہ یہ حواکی بیٹی کی داستان ہے۔ ڈاکٹر انور سجاد عورت کو زمین سے مشابہہ قرار دیتے ہیں کیونکہ زمین میں عورت میں کئی قدریں مشترک ہیں سب سے بڑی قدریہ کہ دونوں ہی تخلیق کے کرب سے گزرتی ہیں اور یہ کرب نہ ختم ہونے والی حقیقت ہے۔ سخت زمین کو کھود کر اس کے نیچے نرم اور گیلی مٹی تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اس طرح انور سجاد اپنے ناولوں میں عورت کے اندر جھانک کر اس کے دکھ اور کرب کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس کرب کا ذمہ دار مرد کا جبر اور اس کی حاکمیت ہے۔ عورت کی زمین سے مشابہت مصنف کی منفرد سوچ کی عکاس ہے۔ زمین اپنی ظاہری ساخت میں مظلوم ہے کیوں کہ اس کے اوپر ہر طرح کا ظلم اور تشدد روا رکھا گیالیکن پھر بھی اس کی زبان پر حرفِ شکایت نہیں۔ انور سجاد نے "جنم روپ" میں بعض مقامات پر عبارت کو اس انداز سے لکھا ہے جیسے وہ نظم کے مصرعے ہوں جبکہ ناول کا اسلوب نظم کے اسلوب سے مختلف ہوتا ہے۔ شاید انور سجاد کے لاشعور میں شاعری بستی ہے اور شعور میں آکر وہ ناول کا روپ دھار لیتی ہے۔ وہ مصوری سے متاثر ہیں اور مصوری کی زبان میں ناول تخلیق کرتے ہیں۔
"گھٹی فضاوں میں گھنی جھاڑیوں کے بیچ جگنو
سیاہ زمین پر خشک پتوں کے بوجھ تلے دبے قمقموں والے کیڑے
اور ضیف النفس ستارے جو ایک وقت میں پر اسرار
ارضِ آدم کے نصف کُرے پر روشنی بچھاتے ہیں۔" (۳)
انور غالب کا نام بھی اسی قبیلے میں شامل ہے جنہوں نے ناول میں نئے تجربات کی شروعات کی ہیں۔ "ندی" (۱۹۸۱ء) بھی شاعرانہ اسلوب کا حامل ناول ہے۔ اس ناول کے کردار اپنے وجود میں قائم ہونے کے باوجود جداگانہ علامتی حیثیت بھی رکھتے ہیں جن کی بدولت انور غالب انسانی نفسیات کی کیفیات کو اجاگر کرتے ہیں۔ انور غالب کے ناول میں شاعرانہ اسلوب کی مثال ملاحظہ ہو۔
"میں شہر میں اتنی بڑی کوٹھی میں رہتی ہوں میں کیا باتیں سناوں جب
میری کُٹیاہوگی، کھلے کھلے خوبصورت سبز سنہرے میدان ہوں گے ندی کنارے
بیٹھا کروں گی تو تنہائی میں کتنی باتیں سیکھ جاوں گی۔
صبوح نے تعجب سے ندی کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا
ہیرے کی مانند یہ شبنم کا قطرہ تنہا،میرا من ہانپنے لگا ہے
کیوں گراہے میرے دل پر کیوں اس نے انتخاب کیا ہے مجھے
دیکھ پاوں گی قطرہ قطرہ"(۴)
عورت اُردو ناول کا مخصوص موضوع رہا ہے معاشرے میں اس کے ساتھ ہونیوالی نا انصافی اور ظلم و ستم کو بہت سے ناول نگاروں نے بیان کیا ہے۔ انور سن رائے نے "ذلتوں کے اسیر" (۱۹۹۸ء) میں ظلم و زیادتی کی اس روداد کو بڑے حقیقی انداز میں پیش کیا ہے ان کے پہلے اور دوسرے ناول میں تقریباً دس سال کا وقفہ ہے۔ "چیخ" (۱۹۸۷ء) مارشل لاء کے دور میں ہونے والے مظالم کا منظرنامہ ہے۔ انور سن رائے مارشل لاء کے دوران افراد کی نفسیاتی کیفیت کو ان الفاظ میں اجاگر کرتے ہیں۔
"مجھے اس سے پہلے کسی عدالت میں حاضر ہونے کا ذاتی تجربہ نہیں تھا
لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب ذات ہی نہ ہو تو ذاتی نوعیت کے تجربات کی کیا اہمیت"(۵)
ثریا شہاب کا "سفر جاری ہے" بھی مارشل لاء کے تناظر میں لکھا گیا۔ اس میں مارشل لاء کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کٹھن اور بے یقینی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ بے یقینی، محرومیوں اور انسانی حقوق کے استحصال کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے مثلاً
"سمجھوتوں کی اس سرزمین میں اسے ہر طرف ہر شخص اس میں بندھا نظر آتا ہے۔ لوگ کھل کر بات کرنا بھول گئے تھے۔ منافقت کی ردائیں اوڑھ لی تھیں اور کسی بھی شخص کا اصل چہرا پہچانا دشوار ہوگیا تھا۔ ایسے وقت میں پیغمبر تو ہجرت کرجایا کرتے ہیں وہ کیا کرے۔"(۶)
ارشد وحید کا "گمان" (۱۹۹۵ء) خالص سیاسی پس منظر میں لکھا جانے والا ناول ے جو مارشل لاء کے خلاف احتجاج کی روداد ہے۔
"بس جی اب بھٹو دوبارہ آئے گاتب ہی کچھ ہوگا رسول بخش نے کہابھٹو؟ ہاں جی رسول بخش نے زور دیتے ہوئے کہا بس اب بہت ہوگیا جی۔بڑا انتظار ہوگیا جی اب اس نے آہی جانا ہے پھر سب ٹھیک ہو جائے گایہ ضیا تو جی جتنی مرضی گولیاں برسالے کوڑے لگالے پھانسیاں لگالے اس نے تو جانا ہی ہے۔" (۷)
یوں انور سن رائے کا "چیخ" (۱۹۸۷ء) ثریا شہاب کا "سفر جارے ہے" (۱۹۹۵ء) اور ارشد وحدی کا "گمان" (۱۹۹۵ء) مارشل لاء کے جبری دور کو موضوع بناتے ہیں۔
طارق محمود کا "اللہ میگھ دے" (۱۹۸۷ء) رضیہ فصیح احمد کا "صدیوں کی زنجیر" (۱۹۸۸ء) اور مستنصر حسین تارڑکا "راکھ" (۱۹۹۷ء) کا موضوع پاکستان کا قومی المیہ سقوط ڈھاکہ ہے۔ تینوں ناول مشرق کی علیحدگی کے اسباب سے بحث کرتے ہیں۔ مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستانیوں کے استحصال کو ناول نگاروں نے مکمل دیانت داری سے بیان کیا ہے۔ طارق محمود نے سادگی اور سچائی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے واضح کیا ہے کہ بنگلہ تحریک تنظیم بننے کے مراحل تک کسی طرح پروان چڑھی طلبا کے ذہن کس طرح اتحاد کے ٹکڑے کرنے پر مائل ہوئے۔
"سلیم اللہ ہال کے صدر دروازے پر میں نے ایک پوسٹر دیکھا سوشیالوجی ڈیپارٹمنٹ کے پاشا کا ہاتھ بہت منجھا ہوا تھا۔ ایک گائےدکھائی دی جو گھاس کو مشرق پاکستان میں کھا رہی تھی سارا بنگلہ سے رستاہوا دودھ مغربی پاکستان میں بہہ رہا تھا۔" (۸)
رضیہ فصیح احمد کا ناول "صدیوں کی زنجیر" (۱۹۸۸ء) بھی مغربی پاکستان کے رہنماوں کے متعصب رویئے کو بیان کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی مالی صورتحال کو وہ قارئین پر اس طرح منکشف کرتی ہیں۔
"اچھا قالین خریدوگی بڑے اچھے قالین آئے ہوئے ہیں۔ جوٹ کے بنے ہوئے بہت سستے ہیں۔
مگر قالین جائیں گے کیسے؟سب چلے جائیں گے آئے دن مغربی پاکستانیوں کی فرمائشیں آتی رہتی ہیں۔ارے بھئی کراکری کٹلری ڈنر سیٹ قالین فرنیچر کاریں کیا چیز ہے جویہاں سے نہیں جاتی۔ یہاں چیزیں سستی ملتیں ہیں خریدنے والا کوئی نہیں سواے ہم دو چار مغربی پاکستانیوں کے" (۹)
"راکھ" (۱۹۹۷ء) میں مستنصرحسین تارڑ نے سقوط ڈھاکہ کو اپنے جذبات میں ڈھالا ہے۔
"تم میری ڈارلنگ بھرجائی آگاہ ہو کہ اس دسمبر کے بعد میں ہمیشہ فرش پر سوتا ہوں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس میں شاید میری تاریخ کا جبر شامل ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ پروقار طریقے سے ایک چارپائی پر سوسکوں۔"(۱۰)
بانو قدسیہ کا "راجہ گدھ" (۱۹۸۱ء) موضوع کے لحاظ سے تو منفرد ہے لیکن زبان بھی بے حد رواں اور سلیس ہے بانو نے ثقیل الفاظ سے اجتناب برتا ہے۔ چونکہ ناول کا زمانہ جدید ہے اور اس کے کردار اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل ہیں اس لئے وہ اپنی گفتگو میں انگریزی زبان کے الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان کے متبادل لفظ کو استعمال نہ کرکے انہوں نے فضا میں مصنوعی پن نہیں آنے دیا۔
"ہائے پتہ ہے قیوم مجھے پروفیسر سہیل نے بڑا Disappoint کیا۔وہ میرے ہزبنڈ کے ساتھ یونیورسٹی میں ہیں آج کل یاد ہے ناں ہم سب ان کو کتنا Idealize کیا کرتے تھے"۔
میں تو اب بھی انہیں پوجتا ہوں۔"چھوڑو بڑے تکلیف دہ آدمی ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اتنا
چھوٹا Behave کرتے ہیں واقعی؟ ذرا نالج نہیں سارا Mass Media بولتا ہے۔"(۱۱)
بانو قدسیہ کاہی "حاصل گھاٹ" (۲۰۰۳ء) بھی اسلوب کے اعتبار سے ایک مکمل نئے دور کی پیداوار ہے اس ناول میں مسائل کا دائرہ کار بڑھ کر لاہور سے امریکہ تک پہنچ گیا ہے۔ مثلاً جمند کہتی ہے:
"ہم ایک دن Leaf Over’s کھاتے ہیں اور سنڈے کو میں کوکنگ کرتی ہوں اور سارے ہفتے کی Dishes تیار کرکے فریزر میں رکھ دیتی ہوں۔ میرا خیال ہے آپ مائینڈ نہیں کریں گے دیکھیے ناں مجھے بھی
کام پر جانا ہوتا ہے۔ آپ فریزر میں سے کچھ نہ نکالیں اور جو کچھ فریج میں رکھا ہوا ہے آپ مائیکرو ویواون میں ڈال کر گرم کرلیں ہم ڈسپلن سے Organize ہوکر زندگی گزارتے ہیں"۔ (۱۲)
تیزرفتاری، مادہ پرستی امریکہ کا جارحانہ رویہ یہ سب ہمارے نئے آنیوالے ناول کا موضوع ہے جس میں واپس اپنی جڑوں کی تلاش اور اپنی مٹی کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ پسِ پردہ ظاہر ہوتا ہے۔ دیہات کی زندگی کو سکون کے حوالے سے اہمیت دی جا رہی ہے اور علاقائی تشخص کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔
امریکہ کے سپر پاور ہونے اور تمام دنیا پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے رجحان کو ناولوں میں بھر پور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ "حاصل گھاٹ" کے علاوہ مستنصر حسین تارڑ کے "قلعہ جنگی" (۲۰۰۴ء) میں بھی بین الاقوامی صورتحال کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ خطے میں رونما ہونے والے تغیرات، طالبان، پاکستان، امریکہ اور ۱۱ ستمبر یہ سب اس ناول کے مختلف پہلو ہیں۔ چند سر پھرے نوجوانوں کے حوالے سے جہاد کے تصور کو یوں پیش کیا ہے۔
"ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کے یہ ایک ہاری ہوئی جنگ ہے پھر بھی لڑنا چاہتاہوں تصور کامل ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اگر وہ جیت جائے توتصور کامل نہیں ہوتا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کے لئے مرنے والوں کی موت مکمل ہوتی ہے جب کہ جیت جانے والے ہمیشہ بے یقین موت مرتے ہیں۔"(۱۳)
تارڑ کے ناول زبان و بیان کے لحاظ سے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ خصوصاً "بہاو" (۱۹۹۲ء) "راکھ" (۲۰۰۱ء) "قربتِ مرگ میں محبت" (۱۹۹۷ء) کے حوالے سے ہم پنجابی الفاظ کی ایک لغت تیار کرسکتے ہیں۔ تارڑ کے ناولوں میں پورا پنجاب جھلکارے مارتا ہے۔
"نیچے ہر یا دل سے نچڑے ہوئے گھنے رکھ تے جو اس کے پاس آرہے تھے۔ وہ اور نیچے ہوا تو رکھوں کے ذخیرے میں گھری ایک جھیل دکھائی دی پر اس کا پنای لشکتا نہ تھا۔" (۱۴)
"قربتِ مرگ میں محبت" میں معاشرے کے اہم سماجی مسئلے کی طرف اشارہ ہے اور وہ نوجوان نسل کا زندگی کی مصروفیات میں گم ہوجانا اور اپنے بزرگوں کو نظر انداز کرنا ہے۔
"اس کے بچے اس کی بیٹیاں ہمیشہ رات کے اس پہر اسے فون کرتی تھیں کہ یہ اقتصادی طور پر انہیں موافق آتا تھا، ہیلو ڈیڈی آپ سو تو نہیں گئے تھے۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا۔ میں ثانیہ بول رہی
ہوں آواز آ رہی ہے ناں۔ آریو آل رائٹ ڈیڈی، بلڈ پریشر کی گولی کھالی ہے، سستی نہیں کرنا ڈیڈی آئیی لو یو ٹیک کیئر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بائے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔"(۱۵)
بزرگوں کو معاشرے کا ایک مفلوج طبقہ سمجھنا اور ان کو یکسر نظر انداز کردینا اسی پہلو کو اکرام اللہ نے "سائے کی آواز" میں پیش کیا ہے۔
"گیارہ بجے بیٹا اندر سے نکلے گا اور گاڑی سٹارٹ کرکے زن سے کلب برج کھیلنے نکل جائے گا اور شام کو پانچ چھ بجے لوٹے گا، پھر بیوی کو لے کر جائے گا تو دس گیارہ بجے کے قریب واپسی ہوگی۔ باپ کے جانے کے بعد بڑا پوتا موٹر سائیکل پر دوستوں کوملنے چل پڑے گا چھوٹے پوتے کے ساتھی آجائیں گے اور لان میں کرکٹ ہوگی۔ تین چار بجے کوئی نہ کوئی بہو کی ملنے والی آن ٹپکےگی۔ ایک مجھے نہ کہیں جانا ہے اور نہ کسی کو مجھے ملنے آنا ہے مجھے اب کچھ کرنا ہے اپنے اندر ہی کرنا ہے۔ باہر کچھ نہیں کرنا۔ غنیمت ہے کہ اندر بھی آباد ہے۔" (۱۶)
انیس ناگی کے موضوعات پاکستان کے سماجی مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان کے ناولوں کے کردار معاشرے کے ساتھ مفاہمت نہیں کرسکتے۔ ان میں ناول "دیوار کے پیچھے" (۱۹۸۰ء) کا ہیئرو پروفیسر"میں اور وہ" (۱۹۸۹ء) کا ہیرو "محاصرہ" (۱۹۹۲ء) کا سلیم "دارلشکوہ" (۱۹۹۸ء) کا میجر قربان "قلعہ" (۱۹۹۴ء) کا کیمپ شامل ہیں۔ "ایک گرم موسم کی کہانی" (۱۹۹۰ء) میں تاریخ کے ایک اہم واقعہ ۱۸۵۷ء کے غدر کو موضوع بنایا ہے۔
"قصور لوگوں کا نہیں ان کا ہے جنہوں نے انہیں بے بس کردیا۔ ایک صدی سے ملک خانہ جنگی کا شکار ہے۔ کھبی مغلوں کے شہزادے آپس میں لڑتے مرتے رہے پھر مرہٹے، سکھ، گورے عام آدمی نےسب دکھ اٹھایا ہے وہ کس طرح دہلی کے بادشہ کے لئے کچھ قربان کرسکتے ہیں جس کا چہرہ کھبی رعایا نے نہیں دیکھا۔"(۱۷)
قرۃ العین حیدر نے "گردش رنگ چمن" (۱۹۸۴ء) اور "چاندنی بیگم" (۱۹۸۹ء) میں پلاٹ کی بنیاد دستاویزی مطالعہ کے بعد اٹھائی۔ ان دونوں ناولوں میں مخصوص جاگیرداری نظام کی توڑ پھوڑ، تقسیم کو قبول کرتے ہوئے برصغیر کے لوگوں اور حکمرانوں کے ذہن کو سمجھتے ہوئے انگریزی کی حکمرانی کو صحیح قرار دینے والے نوجوان نسل ہے۔ جو ماضی کی غلطیوں سے سیکھ رہی ہے اور حقیقت پسند رویئے کی حامل ہے۔
جمیلہ ہاشمی نے "دشتِ سوس" (۱۹۸۳ء) میں حقیقت پسند کرداروں کی نفسیاتی تحلیل کی ہے اور اپنے ناولوں میں عورت کی داخلی کیفیات کی تصویر کشی کی ہے۔
فہمیدہ ریاض کے کراچی (۱۹۹۶ء) کا موضوع شہر کراچی کی سیاسی صورتحال، دہشت گردی، قتل و غارت اور بدامنی ہے۔ مجموعی طور پر بیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں کے دوران منظر عام پر آنے والے ناولوں کے موضوعات و رجحانات فرد کی تنہائی، ناآسودگی، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال، افغان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان میں پیدا ہونے والے مسائل، تاریخ کے تناظر میں حال کا جائزہ، سقوط ڈھاکہ، سیاسی جبر، سرمایہ دارنہ نظام کی قباحتی، تیسری دینا کے ممالک کا استحصال، اپنی تہذیب و ثقافت سے بے زاری اور مغربی تہذیب کی تقلید، تیز رفتاری اور مادہ پرستی پر مبنی زندگی، بزرگوں سے بیزاری، عورتوں کی سماج میں حیثیت، اپنی جڑوں کی تلاش زیر بحث لائے گئے۔ یہ رجحانات اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ جبر کی فضا میں سانس لیتا ہوا ناول نگار اپنے سماج کی تصویر کشی ناول کے فن کی صورت میں پیش کرنے سے نہیں ہچکچاتا اور یہ حقیقی رویئے کسی بھی صنف کو استناد کا درجہ بخشے ہیں۔
حوالہ جات
۱۔ احمد جاوید، "پاکستانی ادب کی شناخت" عبارت (کتابی سلسلہ) راولپنڈی، ص ۳۱۔
۲۔ انور سجاد، ڈاکٹر، "خوشیوں کا باغ" سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۶ء ص ۲۰۔
۳۔ انور سجاد، ڈاکٹر، "جنم روپ" قوسین لاہور، ۱۹۸۵ء۔
۴۔ انور غالب، "ندی" مکتبہ کارواں، لاہور، ۱۹۸۱ء، ص ۱۴۔
۵۔ انور سن رائے "چیخ" شہزاد پبلی کیشنز، ۲۰۰۱ء ص ۸۔
۶۔ ثریا شہاب، "سفر جاری ہے" سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۵ء، ص ۱۵۵۔
۷۔ ارشد وحید "گمان" گورا پبلشرز، ۱۹۵ء، ص ۱۶۵۔
۸۔ طارق محمود، "اللہ میگھ دے" کاروانِ ادب، ملتان، ۱۹۸۹ء۔
۹۔ رضیہ فصیح احمد "صدیوں کی زنجیر" مکتبہ اسلوب، کراچی، ۱۹۸۸ء، ص ۴۴۔
۱۰۔ مستنصور حسین تارڑ، "راکھ" سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۷ء، ص ۶۰۔
۱۱۔ بانو قدسیہ، "حاصل گھاٹ" سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۳ء، ص ۹۔
۱۲۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ایضاً۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
۱۳۔ مستنصور حسین تارڑ، "قلعی جنگی" سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۲ء، ص ۱۲۴۔
۱۴۔ مستنصور حسین تارڑ، "بہاو" سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۸۔
۱۵۔ مستنصر حسین تارڑ، "قربتِ مرگ میں محبت" سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۱ء، ص ۵۹۔
۱۶۔ اکرام اللہ، "سائے کی آواز" سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۱ء، ص ۴۶۔
۱۷۔ انیس ناگی، "ایک گرم موسم کی کہانی" مکتبہ روہتاس، ۱۹۹۰ء، ص ۱۲۴۔