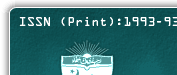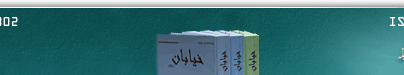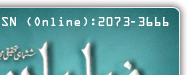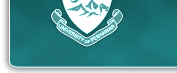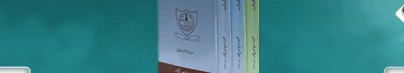فکر اقبال میں جبر و اختیار کا سنجیدہ ترفع
Abstract
Author discusses a very important and serious issue of determination and in-determination with the reference of Iqbal’s thought. He discovers the serious divine and subliminal aspects of this topic with new angles. His discussion negates misinterpretation usually spread in this regard. He supports his observation and arguments with his solid logical style and research oriented methodology. He discovers some sublime aspects of this thought of higher seriousness. مشرق و مغرب کے منکرین اور اہل مذہب، ذات الوہیت کو یا تو دنیوی امور سے بہ رضا ورغبت دست بردار کرکے وراء لے گئے اور خود اُس کے نائب مناب بن بیٹھے یا محرک غیر متحرک بناکر (۱) اور کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری دکھا کر وحدت الوجود کا فنائی الحاد ہی عام نہ کیا، عالم انسانی کے آبِ حیات میں تقدیر انسانی کے حقیقی مفہوم و مقصود سے ناآشنا، بے عمل تقدیر پرستی کا زہر بھی گھولا۔ مسئلہ تقدیر سے جبر و اختیار کی بحث چھڑی اور ایسی ایسی موشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں ہوئیں کہ اس گرد وغبار میں خود تخلیق انسانی کا ازلی مقصود و مفہوم بھی چھپ گیا اور صرف احسنِ تقدیم پر فائز انسان ہی مجبورِ محض نہ ٹھہرا۔ سراپا خیر، ذاتِ احدث سے شر بھی منسوب ہوگیا۔(۲)
اس تیرہ فکری میں اقبال نے اپنی پہلی فارسی مثنوی اسرارِ خودی، مطبوعہ ۱۹۱۵ء میں ع۔ می شود از جبر پیدا اختیار کے اعلان سے جبر و اختیار کی ایسی بحث آغاز کی جو اس سے پہلے کم کم ہی سنائی دی تھی۔ فکرو عمل کی اس تخلیقی رفعت کو پانے تک، تقدیر پرستی کے ان گھنے جنگلوں میں اقبال نے یہ راہ کب پائی۔ فی الوقت اس کا تعین تو شاید آسان نہ ہو۔ البتہ ۱۹۱۰ء میں اقبال کی مرتبہ ذاتی ڈائری کے ایک اقتباس “God and Devil” کی تحتِ عنوان درج شذرہ کو اس گفتگو کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔
Both God and Devil give man opportunities only, leaving him to make use of them in the way he thinks fit.(Stray Reflections page 121)
ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے اس عبارت کا اردو ترجمہ یوں کیاہے۔
خدا اور شیطان دونوں انسان کو صرف مواقع فراہم کرتے ہیں اور یہ اسی پر چھوڑدیتے ہیں کہ وہ ان سے جیسا مناسب سمجھے فائدہ اُٹھائے۔ (شذراتِ فکر اقبال ۱۵۶)
بظاہر یہ سادہ سی عبارت نہ صرف بامقصد زندگی میں خیروشر کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے بلکہ جبر و اختیار کی بے مثال گرہ کشائی سے اقبال کو وجودیوں کے طائفے سے بالکل مختلف، منفرد اور ممتاز فکری مقام پر دکھاتی ہے۔ بلاشبہ علمی اجتہاد سے سیاسی آزادی کے جہدوجہد تک فکرِ اقبال کی تعمیر میں اسی یقین کی گرمی کار فرما رہی ہے۔
اہلِ مغرب نے اس مقام کو "فطری آزادی سے تعبیر کیا اور اس کا حصول کلیسیا کے خود ساختہ الوہی اختیار کے جبرواستبداد سے نجات میں ڈھونڈا لیکن موسٰی سے محمد تک سچی آسمانی ہدایت کے رمز آشنا ہدایت کے رمز آشنا وارث، اقبال کی فکرِ رسا، عیشِ دوام، آئین و شریعت کی پابندی میں دیکھتی ہے اور فطری آزادی کے اس مغربی تصور اور وجودی شعور کو سامانِ شیون، ٹھہراتی ہے۔
دہر میں عیشِ دوام آئیں کی پابندی سے ہے
موج کو آزادیاں سامانِ شیون ہوگئیں (کلیات اقبال اردو ۱۸۷)
کیا واقعی موج آزاد ہے؟ یا اس کی بے مہار آزادی، کسی قاعدے قانون کے جبر سے پھوٹتی ہے؟ اس قاعدے قانون اور اس آئین میں کیا فرق ہے جس کی پابندی موج کے لئے سامانِ مگر عالمِ انسانی میں عیش و دوام، کا سبب ہے۔
کیا شیون سامان موج، اس عیاشی سے شیون واقعی محروم ہے، عالم انسانی میں جس سے دوام، وابستہ ہے؟ یا یہ کہ اس کی یہی شیون سامانی اس کے لئے عیشِ دوام، کا درجہ رکھتی ہے۔ (ہستم اگرمی روم گرنہ روم نیستم)
مذکورہ شعر اقبال میں پائے جانے والی تضاد آفرین گنجل سے اُٹھنے والے یہ سوالات ہی دراصل اقبال کی فکرِ رسا تک رسائی کا وسیلہ اور مقدرِ انسانی کی تفہیم کا ذریعہ ہیں۔ اقبال ہی کا کہنا ہے:۔
اس موج کی قسمت کو روتی ہے بھنور کی آنکھ
دریا سے اُٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی (کلیاتِ اقبال اردو ۴۱۴)
نہیں ساحل تری قسمت میں اے موج
اچھل کر جس طرف چاہے نکل جا (ایضاً، ۳۷۲)
موج کی قسمت (تقدیر) کا یہی جبر تو ہے، جس نے اُس پر لذتِ ساحل حرام، اور اُچھل کر جس طرف چاہے نکل جانے کی فطری آزادیاں، عام کردی ہیں۔ موج کی تقدیر کا یہی جبر تو ہے جو اُسے کوہ وبیاباں میں سیلِ تُندرو اور گلستانوں میں جوئے نغمہ خواں ہوجانا سکھاتا ہے۔ موج ّقطرہ ہائے آب کی یہی اجتماعی تقدیر (جواب تک کے سائنسی انکشافات کے مطابق سطح ہموار رکھنا ہے) موج کو سطح ناہموار ہونے کی صورت میں سرپٹ دوڑنے، آپادھاپی مچانے، اسے بہانے، اُس سے سر ٹکرانے پر، اور ہموار ترائی میں یک لخت پُرسکون ہو جانے پر مجبور کرتی ہے، یہ سطح ہموار یا نا ہموار ہو جانے کا شعور ہو یا دوڑنے اور رُک جانے کی آزادی، تقدیر ہی کا جبر ہے۔ اسی جبر (ہدایت بالذات یا ہدایت بالفطرت) سے موج، موج ہے۔ موج کے ذاتی تشخیص () کا قیام و دوام اور اجتماعی تقدیر کے حصول پر، دولتِ سکینہ سے ہمکنار ہو جانے کا اہتمام، اسی ہدایت بالفطرت سے وابستہ ہے۔ ہائیڈروجن کا جلنا۔ آکسیجن کا جلنے میں مدد دینا۔ تقدیر ہیں اور اسی سے ان کی انفرادی خصوصیات (اعمال) کا شعور پھوٹتا ہے جو ان عناصر کی انفرادی شناخت ہیں اسی سے ان کا دائمی تشخص قائم ہے۔ اگر یہ نکتہ واضح ہو گیا ہو کہ موج کی حرکت و سکون کے شعور اور اس کے تشخیص کی ضامن اُس کی تقدیر (ہدایت بالفطرت) ہے تو پھر تقدیر کا حقیقی مفہوم پانا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی تقدیر، نام ہے عناصر کے مقصدِ وجود کا جو اُنہیں مرحلہ تخلیق ہی میں ودیعت کردیا گیا ہے۔ جس سے سرِ موانحراف ممکن نہیں اور جس میں اس کمالِ استغراق ہی سے ہر عنصر کا ذاتی تشخص (خودی اور انا) قائم و دائم ہے۔
رب العالمین جل شانہ نے اپنے مخاطبِ اول رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ و سلم کی وساطت سے نوعِ بشر کو یاد دلایا ہے۔
سبح اسم ربک الاعلی ہ الذی خلق فسوای ہ والذی قدر فھدٰی ہ والذی اخرج المرعٰی ہ فجعلا غشاءً احوای ہ سنقرئک فلاتنسٰی ہ
(سورۃ الاعلٰی ۸۷ آیات ۱ تا ۶)
ترجمہ: اپنے پروردِگار عالی کی پاکی بیان کرو، جس نے پیدا کیا پھر توازن بخشا، وہ ذات جس نے تقدیر (مقصدِ وجود) اور ہدایت سے نوازا۔ وہ ذات جس نے چارہ اگایا، پھر اُسے سیاہ کوڑا کردیا۔ ہم تجھے (اے رسول!) پڑھائیں گے پھر تو بھی نہ بھلاسکے گا۔
گویا وہ تقدریرات (جو بقول ماہرین طبیعات، طبعی قوانین جاریہ یا اشیاء کی خاصیتیں ہیں) ہر شے کی فطرت کا جزو ہیں اور ہر شے اس ہدایت (قوانین جاریہ یا تقدیرات) کی تابع مہمل اور مجبور محض ہے۔
کیا انسان کی تقدیر بھی یہی ہے اور وہ بھی اپنی تقدیر کا تابع مہمل اور مجبورِ محض ہے؟ جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟
اگر ایسا ہوتا اور اللہ جل شانہ کی یہی منشاء ہوتی تو بلا شبہ تمام بنی نوع انسان ایک ہی امت ہوتے۔
لوشاء اللہ لجعلکم اُمتا واحدہ (المائدہ ۵ آیت ۴۸)
ترجمہ: اگر اللہ چاہتا تو البتہ تہمیں بھی امت بنا دیتا
مگر عملاً ایسا نہیں بلکہ انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے۔ اُس میں اس کی آزمائش مقصود ہے۔
سلکن لیبلوکم فی ماآتکم فاستبقو الخیرات (ایضاً)
نیکیوں میں سبقت لے جانے کی یہ آزمائش خیروشر میں تمیز (اختیار) کے بغیر نہیں ہوسکتی اور مجبورِ محض ہونا (اتباع مہمل) اور خیرو شر میں تیمز کا اختیار یک جا نہیں ہوسکتے۔ معلوم ہوا کہ تقدیر انسانی ان تقدیرات سے قطعی مختلف ہے۔ بلکہ بحث کے اُلجھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو واضح کیا جاتا کہ یہی تقدیرات جو کائنات میں خیر ہی خیر ہیں۔ (کیونکہ سائنسی انکشافات و ایجادات کا استقلال ان ہی تقدیرات پر مبنی ہے جو انسانی زندگی میں وسائلِ آسائش تلاش کرنے میں مصروف ہیں) عالم انسانی یا نفسِ انسان میں وہی شر کے منابع ہیں جن کے اتباعِ مہمل سے بچنا ہی خیرات میں سبقت لے جانا (اِتقاء) ہے۔ یہ تقدیرِ انسانی، شے کو شخصیت بخشتی ہے۔ (سورۃ الدھر ۷۶ آیات ۱ تا ۶)
وہ تقدیر کیا ہے؟۔ سورۃ الا علٰی کی درج بالا آیات ۴ تا ۶ میں اس سوال کا جواب، زبردست جامع و مانع مثال سے دے دیا گیا ہے۔ وہ ذات پاک جس نے چارہ اُگایا پھر اُسے گلاسٹرا کوڑا بنادیا۔ جب سے اب تک وہ ایسا کرنا نہیں بھلاسکا۔ برابر اُگتا، گلتا سڑتا پھر اُگتا چلا آرہا ہے اور چلا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالٰی کے نزدیک ہماری مثال بھی سبزے کی سی ہے (وانبتکم من الارض بناتاً۔ ( سورۃ نوح ۱۴ آیات نمبر ۱۷) سنقرئک فلا تنسی، ہم تھجے اے رسول پڑھائیں گے، تو بھی نہ بھلاسکے گا، یہ ہے و ماینطق عن الھوٰی ان ھوالا وحی یوحی۔ (سورۃ النجم ۵۳ آیات ۳، ۴) کی حقیقت انبیاء ورسل علیھم السلام کسی بھی لمحے ہدایت الوحی سے غافل نہیں رہ سکے، فلاتنسٰی کے ہوتے انبیاء و رسل سے کوتاہیوں کا انتساب، شعور نبوت (تقدیر رسالت) سے بے خبری اور خود کو حدیثِ رسول کی روسے اس امت کے مجوس ثابت کرنا ہے۔ العیاذ باللہ، عام انسانوں کے لئے البتہ یہ ہدایت الوحی، موعظت قرار پائی۔ قبول کرنا یہ نہ کرنا انسانوں کے اختیارِ تمیزی پر چھوڑ دیا گیا۔ اناھدینہہُ السبیل اماشکر اًوّاما کفوراً (الدھر ۷۶ آیت ۴) زبانِ وحی ترجمان سے قل انماانابشر، مثلُکم (الکھف ۱۸ آیت ۱۱۰) کا اعلان کروانے کے بعد آپ کی حیات طیبہ کو اُسوہ حسنہ اور آپ ہی کی اطاعت کو اللہ پاک تبارک و تعالٰی کی اطاعت قرار دینے میں یہی حکمت کارفرما ہے کہ "غیرِ رسول کوئی بھی اور کسی بھی درجہ کا متقی کیوں نہ ہو، خطاوں اور کوتاہیوں سے مبرا نہیں ہوسکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنتہ (الاحزب ۳۳ آیات ۲۱) ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ (النساءً آیت ۸۰) من شرطیہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف یہی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے۔(۳) اس اطاعت میں جتنی پختگی ہوگی۔ خواہشاتِ نفس (نفسِ انسانی کے عناصر ترکیبی کی تقدیرات کے مظاہر مشہود) پر اُتنا ہی تصرف حاصل ہوگا۔ (۴)
شکوہ سنجِ سختی آئیں مشو
از حدودِ مصطفٰی بیرون مرو
(کلیات اقبال فارسی ۴۱)
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کہا لوح و قلم تیرے ہیں
(کلیات اقبال اردو ۲۰۸)
اطاعت گزار انسان (مردِ مسلم) نفس کا مرکب نہیں رہتا، راکب ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اسی حوالے سے اسے مردِ حر سے بھی یاد کیا ہے، اس اطاعت سے ہر طرح کے داخلی خارجی جبر سے آزادی ہی نہیں ملتی۔ عناصر پر حکمرانی اور اختیار بھی حاصل ہوجاتا ہے ع بر عناصر حکمراں بودن خوش است چنانچہ اندر کی ہوا، پانی کی تسخیر سے باہر کی ہوا کا کوسوں دور ساریہ تک پیغام پہنچا دینا اور رقعہ پرنیل کی موجوں کا فوری عمل، کسی اچنبھے کی بات نہیں رہتی۔ اقبال نے اسی حقیقت واقعہ کا انکشاف کیا۔
در اطاعت کوش اے غفلت شعار
می شود از جبر پیدا اختیار
شکوہ سنج سختی آئیں مشو
ازحدودِ مصطفٰی بیروں مرو
(کلیاتِ اقبال فارسی ۴۱)
صرف اور صرف یہی راہ۔ ہر طرح سے پُر امن اور پُر سکون انسانی معاشرے کی تشکیل تک جاتی ہے۔ (صراط مستقیم) انسان، اسفل سافلین سے اُٹھ کر مکر احسنِ تقویم پر فائز اور مسجودِ ملائک کہلانے کا سزاوار ہوسکتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت تکرار کے ذیل میں شاید نہ آئے کہ انسان، عناصر ترکیبی کی مادی تقدیرات کے مظاہر: طبعی تقاضوں اور خواہشاتِ نفس کا تابع مہمل و اسیر بے زنجیر ہونے کے باعث مجبورِ محض ہوتا ہے۔ لیکن آئین و شریعت کا پابند اس اتباع مہمل سے نجات پالیتا ہے۔ لااکراہ فی الدین الایہ (بقرہ آیات ۲۵۶) کا یہی حقیقی مفہوم ہے یعنی فی نفسہِ دین میں کوئی جبر نہیں (۵) بلکہ جبر سے نجات کا واحد ذریعہ احکامِ دن پر عمل ہے۔ معتزلہ نے انتہائی برعکس معانی لئے اور منافقین کے ہاتھ یہ آئین گو سفندی تھماگئے "اپنا مسلک نہ چھوڑو دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو" یہ گونگے شیطانوں کا ٹولہ ہے جسے نہ بدروحنین یاد ہیں نہ طائف کے نخلستانوں میں لہو لہان نعلین کا خیال اور نہ کنتم خیرامتاِ اُخرجت للناس الایاہ (آل عمران آیت ۱۱۰) کا پاس و لحاظ حقیقی مسلمان کے لبوں پر ہر دم یہ صلائے عام ہونی چاہیئے۔ آسمانی شریعت کا پابند خصوصاً اطاعتِ رسول، پر کار بند مردِ مسلم ہی نفس نفس و کائنات کا راکب اور حیاتِ جاوداں کا سزاوار ہو سکتا ہے"۔ علامہ اقابل انسانی تشخص (خودی) کی تعمیر، ضبطِ نفس بذریعہ اطاعتِ الٰہی کے مبلغ ہیں۔ خودی مسلمان ہو تو تدبیر بھی تقدیر ہی کا درجہ رکھتی ہے۔ علامہ کے نزدیک سچی اسلامی بے خودی ذاتی میلانات اور طبعی تقاضوں کو احکامِ الٰہی کے تابع کرنے کی کیفیت ہے۔ (۶) (اقبال نامہ ۳۹۰، مکتوب بنام لسان العصر اکبر الہ آبادی ۲۰ جولائی ۱۹۱۸ء) تقدیر مستقبل کے امکانات ہیں اور شریعت، ان امکانات کے حصول کے لئے حدود متعین کرتی ہے۔ (ایضاً) انسانی تشخص کی تعمیر، استحکام اور دوام کا تعلق بنیادی طور پر اختیار (خروشر میں تمیز) اور آزادی سے ہے، جس کے بغیر نہ ان لیس للانسان الامسعٰی (النجم ۳۵ آیت ۳۹) کی بار آوری ممکن ہے نہ ان اللہ لا یغیر مابقومِ حتٰی بغیر واما بانفسھم (الرعد آیت ۱۱) کی اصولی شرط کے کوئی معانی بنتے ہیں۔ حالت بدلنے کے لئے صلاحیت بدلنا ہی تقدیر انسانی ہے جس سے غفلت و انکار، احسنِ تقویم سے اسفل سائلین میں گرنے پر اصرار کے سوا کچھ اور نہیں۔ علامہ نے اسی لئے اپنے خطبات کے چوتھے خبطہ کا عنوان The Human Ego Freedom and Immortality (یعنی خودی، اختیار اور حیات جاوداں) رکھا۔ اور بحث اس لطیف نکتہ پر ختم کی۔ "خودی کی زندگی اختیار کی زندگی ہے جس کا ہر عمل ایک نیا موقع پیدا کردیتا ہے اور یوں اپنی خلاقی اور ایجاد و طباعی کے لئے نئے نئے مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ (تشکیل جدید الہیات اسلامیہ ۱۸۷)۔ وہی بات جو ۱۹۱۰ء کے شذرات میں لکھی تھی کامل فکری پختگی کے ساتھ دہرائی ہے۔ خیروشر اور جبر و اختیار کا یہی فکری ترفع اقبال کے تصور خودی، کو دنیا بھر کے فلسفہ و متصوفین سے ممتاز کرتا ہے۔ اقبال مقام کبریا اور مقام آدمی کو خلط ملط ہونے نہیں دیتا۔ اپنے پیشرونطشے کے بارے میں اس کا یہ اعلان اسی حوالے سے تھا۔
اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں
تو اقبال اس کو سمجھا تا مقام کبریا کیا ہے
یہ 'تصور خدا' کا باہمی فرق ہے جو ہر دو مفکرین کو ایک ہی طرح سوچنے کے باوجود مختلف اور منفرد گردانتا ہے۔ یہ وہی فرق ہے جس کی طرف زبان وحی ترجمان (صلی اللہ علیہ و سلم) سے یہ اعلان کروایا گیا تھا۔ لا اعبد ماتعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین (سورۃ الکافرون ۱۰۹) اس اعلان کا ہر گز ہر گز یہ مطلب نہ تھا کہ "تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں گے" یہ ابدی اعلان دونوں کے تصور الٰہ اور نتیجہتہ "دین" کے قطعاً مختلف و برعکس ہونے کا اعلان تھا۔ نطشے کے اسلاف کا یہی تصورِ خدا تھا جس نے ہمہ مقتدر فعال لما یریدالٰہ العالمین کو بے دست و پاکر دنیوی امور سے برضا ورغبت دستبردار کرکے ہمہ مقدر نائبین حق تخلیق کئے یا ذرے ذرے میں جاری و ساری دکھا کر، سب کو راہِ فنا پر لگا کر براہِ راست خدا بننے کا شوق فضول بخشا، نطشے ہر دو کا خلاصہ تھا۔ اقبال اسے خود فریبی اور خدا فریبی بتاتے اور صرف اپنی دنیا آپ پیدا کرنے والے سراپا اطاعت بندگانِ خدا کو زندوں میں شمار کرتے ہیں۔ نمبر ۷
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
سرِ آدم ہے ضمیرِ کن فکاں ہے زندگی
(کلیات اقبال اردو ۳۵۹)
حواشی
۱۔ جیسا کہ برٹن رسل نے لکھا
The word cause would be confined to the efficient cause. The unmoved mover may be regarded as final cause. It supplies a purpose for change, which is essentially an evaluation towards likeness with God”
(History of western Philosophy P. 181 BR. Rusell. Union Paper back Books Bostan 1982)
۲۔ حالانکہ ہر مصیبت کو انسان کی ذاتی کمائی بتاتا ہے اور ظاہر ہے مصیبت کسی خیر کا نہیں، شرکا نتیجہ ہوتی ہے۔ وما اصابک من مصیبتہ فبما کسبت ایدیکم (الثورٰی آیت ۳۰) بد قسمتی سے والقدرِ خیرہِ شرہِ من اللہ تعالٰی، کا ترجمہ بھی مجملاً اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے" کرکے مسئلہ اور بھی الجھا دیا گیا اور خیرہِ و شر میں مرجح کی طرف توجہ نہ دی گئی۔ ہِ ضمیر ہے۔ انسان کی نیکی اور انسان کی بدی، کی قدر (اندازہ اور قیمت) اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یعنی نیکی بدی انسانی فعل ہے اور جزا و سزا کا اندازہ اللہ کی طرف سے ہے جنہیں بدلنا سوائے رجوع اور اصلاح کے ممکن نہیں۔ فمن تاب واصلح اس کی مزید وضاحت آگے متن میں آرہی ہے۔
۳۔ جب الدین کے احکام، جبر سے نجات کیلئے ہیں تو ہر طرح کی آزادی و نجات اس کا ماحصل ہونا چاہیئے۔ اسی لئے حکم ہوا۔ مااتکم الرسول فخذوہ وما نھٰکم عنہ فانتھوا و اتقو اللہ ان اللہ شاید العقاب (الحشر ۵۹ آیت ۷) جو غیر رسول کے کسی بھی فیصلے اور حکم کو جو اللہ اور رسول کی مرضی سے متصادم ہو واجب الاتباع، سمجھنے کی نفی کرتا ہے۔
۴۔ فکر اقبال میں تسخیر فطرت، اسی کا نام ہے۔ زندگی کی شب تاریک سحر نہ ہوسکی تو برقِ مضطر کو اسیر کرلینے سے کیا حاصل اور ستاروں کی گزرگاہیں تلاشنے سے کیا سود۔
۵۔ ترجمہ حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی
۶۔ اسی کا نام علامہ کے ہاں، عشق، ہے۔ ع۔ ان المحب لمن یحب مطیع
۷۔ عبث ہے شکوہ تقدیریزداں تو خود تقدیریزداں کیوں نہیں ہے۔
(کلیات اقبال اردو ۶۷۴)
کافر ہے تو ہے تابع تقدیر، مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الٰہی
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
(ایضاً ۳۴۷)
منابع و مراجع
قرآن حکیم کے علاوہ
۱۔ اقبال نامہ (کامل) اقبال اکادمی پاکستان، لاہور ۲۰۰۵ء
۲۔ تشکیل جدید الہٰیات اسلامیہ اردو ترجمہ سید نذیر نیازی، بزم اقبال لاہور
۳۔ شذراتِ فکر اقبال اردو ترجمہ، ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۷۳ء
۴۔ کلیاتِ اقبال/ فارسی شیخ غلام اینڈ سنز، لاہور
5. Reconstruction of Religious thought in Islam Stray Reflections of Iqbal Ed: Javed Iqbal, Iqbal Academy Lahore 2006