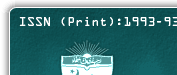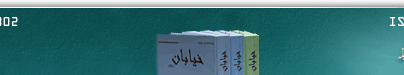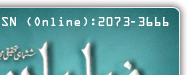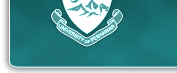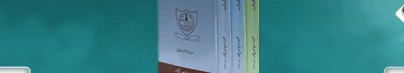اُردو کے فروغ اور اس کے نفاذ کے لیے ہندوستان کی دیگر انجمنوں اور تحریکوں کے ساتھ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی شراکت
Abstract
Paper analysis the relations of all India Muslim educational conference with other associations and literary movements of sub-continent. Paper also evaluates the effect of these relations on Urdu language and literature.
جب زندگی بے رنگی اور فرسودگی کا شکار ہوکر ایک ہی ڈگر پر چلتی رہے تو اس حالت کو جمود کا نام دیا جاتا ہے اور یہ جمود ارتقا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جس سے انسان اضمحلال میں مبتلا ہو کر بلا آخر ذہنی موت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ انسانی فطرت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لمبے عرصے تک یکسانیت اور یک رنگی قبول نہیں کرسکتی۔ اس میں تغیر کی خواہش جنم لیتی رہتی ہے۔ ارتقاء کائنات کے بیشتر زاویے تغیر کے مرہونِ منت ہیں۔ تحریک اس تغیر کی خواہش کو نہ صرف تکمیل کی راہ دکھاتی ہے بلکہ انسان کو جبلی سطح پر آسودگی بھی مہیا کرتی ہے۔ بڑی بڑی تحریکوں میں بھی بنیادی سبب تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے اور یہاں مرکز تحریک فرد کے بجائے پورا معاشرہ ہوتا ہے۔ کسی تحریک کی کامیابی میں زمانے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ تحریک کا بنیادی نظریہ تو ایک بیج کی مانند ہوتا ہے، جس کی نموکے لیے مناسب مٹی اور آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اگر زمین ذرخیز اور طبعی حالات موافق ہوں تو یہ بیج جلد جڑ پکڑ لیتا ہے جو گہرائی تک زمین کے سینے کو سینچے اور دبے ہوئے بیج کو مناسب مواقع فراہم کرے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جو فکرو نظریے زمانے ماسبق میں مقبول نہ ہوسکے لیکن کئی سو سال بعد تحریک پیدا کرنے میں کامیاب ہوگئے مثلاً افلاطون کی مثالی ریاست کا نظریہ اپنے دور میں خاص اہمیت حاصل نہ کرسکا لیکن بیسویں صدی تک پہنچا تو ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر گیا(۱)۔ لفظ اور زبان کے ذریعے سے ہی تحریک کا پیغام عام ہوتا ہے اور پھر اپنے وابستگان کے احساسات جذبات کو متحرک کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ ادب کا وسیلہ بھی لفظ ہے اور اس کا اساسی تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ تحریک چونکہ کسی نہ کسی رنگ میں معاشرے کو متاثر کرنے کا رجحان رکھتی ہے اس لئے ایک مخصوص دائرے کار میں رہتے ہوئے تحریک ادب سے استفادہ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ یہاں یہ بات پیشں نظر رہے کہ ادب قوموں، ملکوں اور لوگوں پر اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ جس طرح ایک معاشرتی تحریک معاشرے کے جمود کو توڑتی ہے اسی طرح ادبی تحریک اس ادب میں تحریک پیدا کرتی ہے جس میں یکسانیت غالب آچکی ہو۔ ادبی تحریک کے لئے ادباء کے ایک وسیع حلقے میں فکرو احساس اور تخلیقی عمل میں ہم آہنگی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ادباء میں یہ ہم آہنگی جتنی زیادہ اور دیرپا ہوگی تحریک اتنی ہی توانا اور طویل العمر ہوگی اور انسان کو نئی بصیرت و آگہی اور نیا ادبی شعور اور تہذیبی رفعت سے ہم کنار کرنے میں مدد دے گی۔ ادب اپنا خام مواد معاشرے سے اخذ کرتا ہے اور تخلیقی عمل سے گزرنے کے بعد بالواسطہ طور پر معاشرے کو ہی متاثر کرتا ہے۔ اس لئے ادب کی ہر تحریک بالعموم عمرانی تحریک ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ تمام محرکات جو کہ بڑی عمرانی تحریک کو پیدا کرتے ہیں وہ ادبی تحریک کو فروغ دینے میں بھی معاونت کرتے ہیں اور ادبی تحریک زبان کے وسیلے سے صداقتوں کی وضاحت اور انہیں نئی معنویت عطا کرتی ہے۔ جس طرح ادب انسان اور معاشرے کو منقلب کرتی ہے۔
ہندوستان میں اردو زبان و ادب کی تشکیل اور ارتقا میں بہت سی تحریکوں نے حصہ لیا جن میں ریختہ کی پہلی تحریک، صوفیا کی تحریک، بھگتی تحریک، ریختہ کی دوسری تحریک، ایہام کی تحریک، اصلاح زبان کی تحریک، ایہام گوئی کی دوسرے تحریک، فورٹ ولیم کالج کی تحریک اور دلی کالج کی تحریکیں اہم ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی ناکامی نے ہندوستانی معاشرے کو ہر سطح پر متاثر کیا اور خاص طور پر مسلمانوں کو اس کا زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ان کی تہذیب و ثقافت، تعلیم و طرز معاشرت، زبان و ادب پر اس انقلاب نے گہرے نقوش ثبت کیے۔
ان حالات میں علی گڑھ تحریک نے مسلمانانِ ہند کی پسماندگی کو تعلیم کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی اور مدرستہ العلوم کے ذریعے ان کی بصیرت کو بدرجہ اتم بڑھایا۔ سانئٹیفک سوسائٹی کے ذریعے جدید علوم اور مغربی ادب کی کتب کو اردو میں ترجمہ کروا کر شائع کیا گیا تاکہ مسلمان جدید سائنسی علوم کی طرف راغب ہوں۔ تراجم کہ ذریعے اُن علمی خزانوں کو مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا دیا جو پہلے یورپ کے کتب خانوں میں موجود تھے۔ تہذیب الاخلاق کے ذریعے ذہنی انقلاب کی راہ ہموار کی گئی۔ ۱۸۸۶ء میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لئے ہندوستان کے گوشے میں اجلاس کرکے ان کو اس طرف راغب کیا۔ دوسری طرف اس پلیٹ فارم سے اردو زبان کو وسعت ملی۔ اردو ادب کے اسلیب بیان اور روحِ معانی بھی متاثر ہوئے اور اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع تر ہوگیا۔ اس کی ادبی ساخت کو مسلمانوں کے تہذیبی اثرات اور عربی اور فارسی کے عناصر نے ایک لسانیاتی انقلاب پیدا کیا (۲)۔ نئے دور میں جدید ہندی کی تحریک جو درحقیقت سنسکرت کے احیاء کی تحریک تھی چل پڑی اور اس کے درپردہ اردو مخالف نظریات کار فرما تھے۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس نے نہ صرف ہندی زبان کے غلبے کو روکنے کی کوشش کی بلکہ اس نے لفظ کی داخلی حرکی قوت کو پہچانا اور انسی ٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الا خلاق کے ذریعے اس قوت کو مثبت طور پر استعمال کیا۔ جس طرح اٹھارہویں صدی کو شاعری کی صدی کہا جاسکتا ہے جس میں بڑے بڑے شعراء نے اردو شاعری اور خاص طور پر غزل کی ایک توانا تحریک کو فروغ دیا۔ اسی طرح انیسویں صدی میں علی گڑھ اور آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے اردو نثر کا ایک باوقار، سنجیدہ اور متوازن معیار قائم کیا اور اسے سادگی اور متانت کی ڈگر پر ڈال کر ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت کو ابھرا، لفظ کے حسن کو اجاگر کرنے کے بجائے روح اور معنی کو اہمیت دہی۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس و علی گڑھ کے نظریے کی حمایت اور مخالفت میں ہندوستان میں بہت سی تحریکیں سامنے آئیں جن میں سے چند کو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔
انجمن پنجاب کی تحریک:
اس تحریک میں مولوی کریم الدین احمد، پنڈت من پھُول، مولوی سید احمد دہلوی، الطاف حسین حالی، پیارے لال آشوب، درگا پرشاد نادر اور محمد حسین آزاد جیسے ادباء شامل تھے۔ انجمن پنجاب کی آواز دوسرے صوبوں تک پہنچانے کے لیے رسائل جاری کیے گئے۔ انجمن کا اہم کام یہ تھا کہ اس نے مختلف مضامین پر ہفتہ وار مباحثوں کا سلسہ شروع کیا جو انتہائی کامیاب رہا۔ انجمن نے اورینٹیل یونیورسٹی کے تجویز حکومت کو پیش کی اور عوامی حمایت اور مطالبے کے بل بوتے پر اس کا قیام عمل میں آیا انجمن پنجاب کی یہ کامیابی اتنی نمایاں تھی کے اس نے صوبے پنجاب کے علمی و ادبی ماحول پر مستقل اثرات ثبت کیے(۳)۔ انجمن کے ابتدائی جلسوں میں مولوی آزاد، پنڈت من پھول، مولوی عزیز الدین، بابو چندر ناتھ، اور پروفیسر علمدار حسین وغیرہ نے مضامین پڑھے اور ان میں سے بیشتر مضامین کی اشاعت رسالہ انجمن پنجاب میں ہوئی۔ انجمن کو کامیاب بنانے میں اس کے مشاعرے کو بھی اہمیت حاصل ہے جو ۷۶۔ ۱۹۷۵ء کے دوران شروع کیے گئے اور اس میں محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، انور حسین ہما، ولی دہلوی اور منشی الہٰی بخش رفیق وغیرہ نے مختلف موضوعات پر نظمیں پڑھیں۔ آزاد اردو زبان کے گرد کوئی جامد حصار باندھنے کے حق میں نہیں تھے بلکہ اس کی ترقی اور فروغ کے لئے بدیسی زبانوں بالخصوص انگریزی سے استغادہ کے قائل تھے اور مطلب اور مضامین کو صرف نثر میں بیان کرنے کے بجائے نظم میں بھی ترویج دینا چاہتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ سرسید احمد خاں کے نظریات سے متاثر تھا کیونکہ سرسید نے مسلمانوں میں اس رجحان کی ترویج کے لئے تمام تر توجہ صرف کردی تھی۔ وہ اور ان کے رفقاء اُردو نثر میں بنیادی تبدیلیوں کے ساتھ موضوعات کے تنوع کے قائل تھے انجمن پہنجاب کے پلیٹ فارم سے اردو شاعری میں انقلابی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ مولانا حالی مشاعرہ انجمن کے کامیاب اور مقبول شعرا میں سے تھے انجمن کے مشاعرہ کی بدولت اردو نظم میں نہ صرف انقلاب بپا ہوا بلکہ شاعری کو فطرت اور صداقت کے قریب تر لانے میں اس نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ شاعری میں غزل کے تسلط اور تنقید و تحقیق میں تذکرہ نگاری کی حاکمیت کو ختم کرنے کوشش انجمنِ پنجاب کے پلیٹ فارم سے کی گئیں۔ انگریزی علوم کے فروغ نے اس تحریک کو قوت بخشی اور یوں نہ صرف لفظ کے نئے استعمال کا آغاز ہوا بلکہ احساس و اظہار میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔
سندھ محمڈن ایسوسی ایشن:
علی گڑھ تحریک نے برصغیر کے تمام صوبوں کے مسلمانوں میں بیداری کی روح پھونک دی تھی اس میں سندھ نہ صرف شامل تھا بلکہ عملی طور پر اس تعلیمی و ادبی تحریک کے زیر اثر یہاں جو کاوشیں ہوئیں انھوں نے سندھ کے علم و ادب کو کئی خوب صورت رنگ دیئے۔ ۱۸۸۲ء حسن علی آفندی نے شمالی ہند کا دورہ کیا اور سرسید احمد خاں سے ملے۔ واپسی پر انھوں نے اپنے رفقا سے صلح و مشورے کے بعد ۱۶ مارج ۱۸۸۴ء میں سندھ محمڈن ایسوسی ایشن کی داغ بیل ڈالی اور اس کا بنیادی مقصد سندھ کے مسلمانوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھانا اور ان کی تعلیمی بہتری کے لئے کام کرنا تھا۔ ابتدا میں اس ایسوسی ایشن، کے ممبرز کی تعداد ۶۳ تھی جن میں اللہ بخش ابوجھو، خان بہادر نجم الدین، سردار محمد یعقوب، شیخ محمد اسمٰعیل، خان بہادر خداداد خان، ولی محمد حسن علی، شیخ صدیق علی، سیٹھ علی بھائی کرم جی وغیرہ شامل تھے۔
حسن علی آفندی ایسوسی ایشن کے پہلے صدر اور مولوی اللہ بخش ابوجھو جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ انھوں نے پورے صوبے کے دورے لیے اور ایسوسی ایشن کی برانچیں صوبے بھر میں قائم کیں۔ ان شاخوں کے صدور ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہوتے تھے۔ ایسوسی ایشن کا صدر دفتر کراچی میں قائم کیا گیا۔ لیکن ۱۹۱۷ء میں جب خیر پور ریاست کے وزیر شیخ ابراہیم اس کے صدر منتخب ہوئے تو ایسوسی ایشن کا صدر دفتر سکھر منتقل ہوگیا۔ ۱۸۹۹ء میں ایسوسی ایشن نے ایک ہفت روزہ اخبار، معاون، کا اجر کیا اس کے ادارت کے فرائض شمس الدین بلبل کے سپرد تھے۔ اس ہفت روزے نے سندھی مسلمانوں میں علمی و ادبی رجحان پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا(۴)۔
رومانی تحریک:
مجموعی طور پر علی گڑھ تحریک نے ادب میں جو تحریک پیدا کیا تھا اس نے پرانے ادبی نظریات کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ اس تحریک کی عقلیت پسندی اور جامد اجتماعیت کے نظریات نے ادب کو نئے موڑ سے روشناس کروایا اور فلسفہ اور سائنس کے استفادے سے اجتماعی بہبود کا راستہ ہموار کیا اور حقیقت پسندی کو فروغ دیا۔ تاہم برصغیر کی اقوام نے ماضی کی روایات سے یکسر ناطہ نہ توڑا اس لئے بہت جلد اس تحریک کے خلاف رومانی نوعیت کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہوگیا۔ جذباتی سطح پر اس ردعمل کو مثبت صورت میں محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر اور میر ناصر علی دہلوی نے ابھارہ اور ان اسلیب کو فروغ دینے کی کوشش کی جن میں ادیب کا تخیل جذبہ کی رو کے ساتھ چلتا ہے۔ اُردو شاعری میں نظم کے فروغ نے غزل کو بھی وسعت عطا کی۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ نظم نے اردو غزل کو نئے آفاق سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان شاعروں نے نہ صرف فطرت کے حُسن کو اپنا موضوع بنایا بلکہ اس کا رشتہ اپنے داخل سے بھی قائم کیا اور تخلیقی سے اس انوکھی اور پُر اسرار روح کو دریافت کرنے کی سعی کی جس کی لطافت اور جاذبیت ذرے ذرے میں پوشیدہ تھی۔
رومانی شعراء میں حفیظ جالندھری کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ انھوں نے شاعری کی تخلیق میں بے فکری، خود نظری، لطافت، نزاکت، خوشی حاصل ہو جانے پر خوشی، رنج و نم سے دوچار ہوجانے پر غم، مسکراہٹ اور آنسو سب کچھ شامل تھے۔ ان کی شاعری کے بیشتر ماخذات مشرقی ہیں ان کی رومانیت کو مشرق پسندی کے اس رجحان کا ایک زوایہ قرار دیا جاسکتا ہے جس کی فروغ میں مہدی افادی، سجاد انصاری اور ڈاکٹر بجنوری نے اہم حصہ لیا۔ جوش ملیح آبادی کی رومانیت میں جذبے کی شدت سے سیاسی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے بقول وہ بیک وقت شاعر شباب ہیں اور شاعر انقلاب بھی، (۵)۔ اختر شیرانی رومانیت کی ان آوازوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے ہاں زندگی ایک ایسا عمل ہے جیسے نسوانی حسن ہی کروٹ دے سکتا ہے۔ انھوں نے عورت کو جو پہلے پردے میں محصور تھی شاعری کی خارجی سطح پر پیش کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کے رومان ایک ایسا لفظ بن گیا جو محبت کا ہم معنی تھا۔
رومانی تحریک سے وابستہ نقاد رومانی طرز احساس کو بڑی خوبی سے تنقید میں استعمال کرتے ہیں جن میں مہدی افادی، عبدالرحمٰن بجنوری، نیاز فتح پوری، عبدالماجد دریا آبادی اور فراق گور گھپوری اہم ہیں۔ اس تحریک نے لفظ اور خیال کی نئی جہتوں کو دریافت کیا جذبے کو بلند پروازی سکھائی اور ادیب کو اپنے خارج سے داخل کی طرف جھانکنے اور پھر تخیل سے ان دونوں میں فنی امتزاج پیدا کرنے کی راہ دکھائی۔
ترقی پسند تحریک:
علی گڑھ تحریک کی عقلیت پسندی کی زیر اثر ادب کی راہیں دو ہوسکتی تھیں(۶) ایک یہ کہ سائنٹفیک انداز میں حالات کو سمجھا جائے اور اسی انداز میں پیش کیا جائے لیکن یہ انداز صرف علمی موضوعات کے لئے مروج ہوا۔ دوسری طرف ادب برائے ادب کے بجائے ادب برائے زندگی کے فلسفہ نے جنم لیا۔ مارکسزم اور سوشلزم وغیرہ نے ہر طرف ایک نیا انداز فکر پھیلا دیا تھا۔ یہ انداز فکر اگرچہ ہندوستنانیوں کے لیے بالکل نیا تھا مگر پھر بی اس میں متاثر کرنے کی صلاحیت تھی اور سب سے پہلے جو طبقہ اس نئے فلسفلے سے اثر پذیر ہوا وہ ادیبوں کا تھا(۷)۔ ۱۹۳۵ء میں پیرس میں بین الاقوامی ادیبوں کی کانفرنس منعقد ہوئی جس کی پہلی کانفرنس منشی پریم چند کی زیر صدارت ۱۹۳۶ء میں لکھنو میں ہوئی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد ادب یں سائنسی مسائل (بھوک، افلاس، سماجی پستی اور غلامی وغیرہ) کو اپنا موضوع بنانا تھا(۸)۔ اس تحریک میں سجاد ظہیر، منشی پریم چند، آنند راج، ایم ڈی تاثیر، فیض احمد فیض، حسرت موہانی، عبدالحق، قاضی عبدالغفار، ڈاکٹر علیم اور ڈاکٹر اعجاز وغیرہ شامل تھے۔ احمد عباس، علی سردار جعفری، اختر حسین رائے پوری، چراغ حسن حسرت، کرشن چندر اور ظہیر کاشمیری وغیرہ وغیرہ بعد ازاں اس میں شریک ہوئے۔ ترقی پسند تحریک بیسویں صدی کی ایک منظم، فعال اور موثر تحریک تھی۔
حلقہ ارباب ذوق کی تحریک:
حلقہ ارباب ذوق ۱۹۳۸۔ ۱۹۳۹ء کے قریب وجود میں آیا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پنسد تحریک کو عام طور پر ایک دوسرے کی ضد قرار دیا جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ داخلیت اور خارجیت، مادیت اور روحانیت، مستقیم ابلاغ اور غیر مستقیم ابلاغ کی بنا پر ان دونوں تحریکوں میں واضح حدودِ اختلاف موجود ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے ابتدائی دور میں میراجی کے علاوہ قیوم نظر اور یوسف ظفر نے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ ادب کے متعلق حلقہ کا نظریہ تھا کہ، ادب قائم بالذات اور اپنی منتہا آپ، ادب زندگی سے گہرا تاثیر لیتا ہے لیکن یہ کسی مخصوص نصب العین کے حصول کے لئے تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا۔ اس کی اپنی جمالیاتی اقدار ہیں اور ادیب ان اقدار کی پابندی کو ملحوظ رکھ کر زندگی کے حسن کو اجاگر کرتا ہے کیونکہ فن، زندگی چھوڑ کر جس سے جی چاہے لیٹ جائے بہر صورت فن ہی رہے گا(۹)۔ حلقہ اربابِ ذوق نے زندگی کے تنوع اور اس کے داخلی حسن کو اہمیت دی اور کسی موضوع پر اظہار کی قدغن نہیں لگائی۔ اس لئے اس تحریک نے سائنسی کی خرد افروزی کو اجاگر کرنے کے ساتھ انسان کے داخل میں آباد دنیا کو دریافت کرنے کی بھی سعی کی۔ اردو ادب میں تنوع توانائی اور رعنائی پیدا کی۔ اس تحریک کا ایک سرا زندگی سے اور دوسرا فن سے ملا ہوا تھا فنی سطح پر تحریک نے ادب پاروں میں ہنگامی تاثر سمونے کے بجائے دوامی حسن میں سمونے کی کاوش کی۔
تحریک ادب اسلامی:
انسانی فکر کو جن دو مذہبی تحریکوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ عیسائیت اور اسلام کی تحریک ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت نے نہ صرف اسلام نے تہذبی پہلو کو اجاگر کیا بلکہ ملک کے لسانی اور ادبی ذخیرے پر بھی اثر ڈالا(۱۰)۔ اُردو زبان چونکہ مسلمانوں کے عہد اقتدار میں پروان چڑھی اس لیے اسے بالعموم مسلمانوں کی زبان تصور کیا گیا۔ اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ اردو زبان و ادب میں اسلامی تحریک روز اول سے جاری تھی(۱۱) اور اس کے فروغ میں خاندانِ ولی اللہ کے تراجمہ قرآن، مظہر جانِ جاناں، خواجہ میر درد، مومن، حالی، اقبال کی شاعری، شبلی، سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، اشرف علی تھانوی، عبدالماجد دریا آبادی، عنایت اللہ مشرقی اور ابو الاعلٰی مودودی کی نثر تصانیف نے اہم خدمات انجام دیں۔ یہ تحریک ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں رونما ہوئی تاکہ ادب میں اشترا کی اور لادینی نظریات کے داخلے کو روکا جاسکے۔ اس تحریک کے منشور کی داخلی جہت اسلام کی طرف تھی اور یہ تحریک زمینی رشتوں کی یکسرنفی کرکے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی خواہش مند تھی جو اسلام کی اساسی روح کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے۔ تحریک کو ابتدا میں نعیم صدیقی، اسعد گیلانی، ابن فرید، نجم الاسلام اور خورشید وغیرہ جیسے اچھے نقاد ملے جنہوں نے ان مسائل کو حل کرنے اور اشترا کی نظریات کے خلاف اسلامی نظریات کا مضبوط حصار مرتب کیا۔
جب مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے ثمرات واضح ہوکر سامنے آنے لگے تو اس تحریک کے تقریباً سب ہی مخالفین نے اس تحریک کی کامیابی کو تسلیم کیا اور مستقبل نے یہ ثابت کیا کہ سرسید اور ان کے رفقا کا معاشرتی و سیاسی تجزیہ درست تھا۔ انھوں نے سائنسی معلومات کی روشنی میں جدیدیت کو فروغ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرسید نے خواب دیکھا اور پھر اسے پورا کرنے کے لیے دارالعلوم علی گڑھ اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے اقدامات کیے جن کی وجہ سے قوم کے دل میں جداگانہ حیثیت کا احساس پیدا ہوا اسی نے مسلمانوں کو پستی سے نکالنے میں معاونت کی۔
جس طرح اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا احساس نہیں ہوتا اسی طرح اگر مخالف نہ ہوں تو دوستی کی قدروقیمت کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر آدمی سے سب لوگ متفق نہیں ہوسکتے اسی طرح ہر تحریک کو مکمل حمایت نہیں ملی سکتی۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اور علی گڑھ تحریک کے مخالفت میں چلنے والے تحاریک نے اس تحریک کے مقاصد کے حصول اور اس کے پیغام کو عام کرنے میں بلواسطہ طور پر اہم کردار ادا کیا۔
کیونکہ حمایتی اور مخالفین جو کچھ بھی لکھ رہے تھے وہ اردو میں تھا۔ دونوں کا ذریعہ اظہار اردو ہونے کی وجہ سے اردو زبان و ادب خودبخود ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ اردو زبان کے لسانی اور ادبی ذخیرے میں اضافے اور اس کے فروغ میں ان تحاریک نے اپنا اپنا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا اور آج اردو جس منزل پر کھڑی ہے اس منزل تک پہنچانے میں ان تحاریک کا کلیدی کردار ہے اسے اردو کے محققین اور تاریخ فراموش نہیں کرسکتے۔
حوالہ جات
۱۔ Will Derant, The Story of Philosophy, New York 1955 pp 123.
۲۔ نسیم قریشی، علی گڑھ تحریک، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۴۰ء، ص ۳۲۔
۳۔ صفیہ بانو ڈاکٹر، انجمن پنجاب۔ قیام، مقاصد اور تاریخ، مشمولہ اخبار اردو مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد (شمارہ مارچ، اپریل ۲۰۰۴) ص ۱۸۶
۴۔ یوسف خشک ڈاکٹر، سرسید کی تحریک کے سندھ اور سندھی ادب پر اثرات، مشمولہ تحقیقی جرنل فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ اسلامک اسٹڈیز بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ۲۰۰۳ء، ص ۱۲
۵۔ انور سدید ڈاکٹر، اردو کی ادبی تحریک، انجمن ترقی اردو پاکستان ۱۹۸۵ء، ص ۵۱۱
۶۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی، جدید اردو شاعری، اردو دنیا کراچی ۱۹۶۱ء، ص ۲۰۱
۷۔ شارب ردولوی ڈاکٹر، ترقی پسند تحریک: نظریاتی نشیب و فراز، مشمولہ ارتقا ۴۱، ارتقا مطبوعات کراچی ۲۰۰۶ء، ص ۵۴
۸۔ آل احمد سرور، تنقید کیا ہے، اردو اکادمی سندھ کراچی ۱۹۵۰ء، ص ۱۷۱
۹۔ میراجی، بہترین نظمیں، ابتدائیہ طبع ثانی، مکتبہ اردو لاہور ۱۹۴۱، ص ۲۱
۱۰۔ خورشید احمد، تاریخ ادیبات مسلمانان پاکستان و ہند (جلد دہم) مجلس ادب لاہور ۱۹۶۵ء، ص ۶۲۱
۱۱۔ محمد مظہر الدین صدیقی، اسلام اور مذاہب عالم، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۶۵ء، ص ۲۱۰