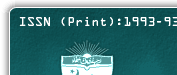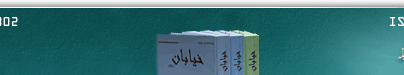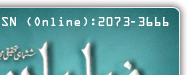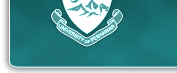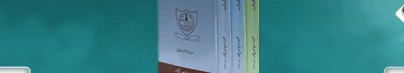محقق پنجاب پروفیسر حافظ محمود شیرانی اور اردو
Abstract
Hafiz Mahmood Sherani is famous researcher of Urdu. His renowned book “Punjab Main Urdu” is under discussion from the time of its publication. During the last seven decades so many writers, critics, linguists, lexicographers give their views about this book. Author summarize the different opinions in this respect and concludes the lexicographic portion of Shirani’s work. This is research oriented findings regarding Shirani’s work.
اردو زبان وادب کے عظیم محققین میں پروفیسر حافظ محمود شیرانی کا نام ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ لیا جائےگا۔ شیرانی صاحب کی تحقیق اگرچہ یورپی تحقیق کے جدید اصولوں پر مبنی نہیں ہے لیکن اردو زبان و ادب کے حوالے سے ان کا کام یقیناً ہمیشہ یاد رکھا جائےگا۔ حافظ محمود شیرانی کو زیادہ شہرت ان کے ایک لسانی دعویٰ نے دی، ان سے منسوب کرکے لوگ یہ کہتے ہیں، اردوزبان پنجابی سے ماخوذ ہے یا آسان لفظوں میں اردو پنجابی زبان سے نکلی ہے، اس دعویٰ میں حقیقت ہے یا نہیں لیکن بلاتحقیق اس کی حمایت اور اس کی مخالفت نے اس کو بے حد مقبول ضرور بنادیا ہے، اس دعویٰ کے حق اور اس کی مخالفت میں بے شمار صفحات سیاہ کیے گئے لیکن ماسوائے شوکت سبزواری کے کسی نے بھی اس کا حقیقی اور بے تعصب جائزہ نہیں لیا۔ شیرانی صاحب کے تحقیقی کام کی وقعت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن شیرانی صاحب ماہر لسانیات نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کہیں سے لسانیات کی بنیادی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی ساری تحقیق لفظوں کی تلاش و تقابل میں نظر آتی ہے۔ اس مقالے میں حافظ محمود شیرانی صاحب کےمقالے "پنجاب میں اردو" کے چند پہلووں کو بعداز تحقیق پیش کیا جارہا ہے۔
حافظ محمود شیرانی صاحب پنجاب میں اردو زبان کے ادب کا ارتقائی مطالعہ کر رہے تھے کہ نصیرالدین ہاشمی صاحب کی کتاب "دکن میں اردو" شائع ہوئی اس کتاب میں اگرچہ یہ دعویٰ تو موجود نہیں ہے کہ اردوزبان دکنی سےنکلی ہے یا پھردکن ہی میں پیدا ہوئی اور دکن سے پورے ہندوستان میں پھیلی لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کچھ ذہنوں میں جو علم لسانیات سے واقفیت نہیں رکھتے تھے انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ چونکہ اردوادبیات کی ابتداء دکن سے ہوتی ہے اس لیے اردو زبان کا آغاز بھی یہیں سے ہوا ہو؟ اسی دور میں کئی ایک مصنفین نے (جوکہ ماہر لسانیات نہیں تھے) اردو اور پنجابی زبان کی قربت کی باتیں شروع کی ہوئی تھیں اس بحث میں علامہ اقبال تک شریک ہوئے جنہوں نے (پنجاب میں کچھ مصالحے) اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا، ایسے میں پروفیسر مسعودحسین خان کی کتاب "مقدمہ تاریخ زبان اردو" منظر عام پر آئی جس می ہریانوی کو اردو زبان کا مآخذ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ان کے اسی کتاب سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو:
"ہندوآریائی لسانیات میں اس عہد کا سب سے بڑا کارنامہ گریرسن کا عظیم الشان 'لسانی جائزہ ہند' ہے۔ گریرسن نے سب سے پہلے بالتفصیل ان قیاس آرائیوں کا ازالہ کیا ہے جو ہماری زبان کے کینڈے کے متعلق بغیر سوچے سمجھے کی گئی تھیں اس نے ہند آریائی زبان کے تاریخی تسلسل کی نشاندہی کی اور جدید آریائی زبانوں کے باہمی رشتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی۔" (1)
گریرسن کی لسانی تحقیقات اردو زبان کے متعلق حرفِ آخر کا حکم نہیں رکھتیں۔ پروفیسر شیرانی جیسے بالغ نظر محقق نے یہ فوراً بھانپ لیا۔ شیرانی کو اپنے نقطہ نظر کے لیے اشارہ خودگریرسن کی تحریروں میں مل گیا تھا جس نے اردو کی "پنجابی پن" پر غیر معمولی زور دیا ہے۔ اس دور میں اردو پر ادبی لسانیاتی تحقیق کا سب سے بڑا کارنامہ پروفیسر شیرانی کی "پنجاب میں اردو" (۱۹۲۸ء) ہے جو ترتیب اور لسانی اصولوں کےاعتبار سے مکمل نہ سہی۔ تحقیق کے اعتبار سے گراں قدر تصنیف ہے۔ خصوصاً پنجاب میں اردو ادبیات کے ارتقائی مطالعہ کے حوالے سے یہ ایک بیش قیمت تحقیقی کام ہے۔
ڈاکٹر محی الدین قادری زور پروفیسر شیرانی کی کتاب "پنجاب میں اردو" پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"پروفیسر حافظ محمود شیرانی اسلامیہ کالج لاہور نے اپنی گراں قدر کتاب "پنجاب میں اردو" میں اردو اور پنجابی دونوں سے متعلق بعض نہایت اہم اور دلچسپ لسانی پہلوؤں پر بحث کی ہے۔ ان کے اہم لسانی دلائل، جن کی بنا پر وہ اردو کو بہ نسبت برج بھاشا کے پنجابی سے زیادہ قریب اور مشترک قرار دیتے ہیں۔ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پنجابی اوراردو دونوں ایک ہی اصول کے تحت لسانی اور نحوی ارتقاء پاتے رہے ہیں۔ فاضل مصنف نے اس سلسلے میں کئی دلچسپ مثالیں اور حوالے پیش کیے ہیں۔ ان کی دوسری دلیل سے واضح ہوتا ہے کہ اردو میں چند اجزا ایسے ہیں جن کا حوالہ سوائے پنجابی کے کسی اور زبان میں نہیں مگر یہ خصوصیتیں براہ راست تعمیر زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ موجودہ اردو میں ان کا کوئی وجود نہیں وہ صرف قدیم دکنی کارناموں میں نظر آتی ہیں۔ پروفیسر شیرانی نے جومواد پیش کیا ہے۔ نہایت ہی مفید اور اردو کی تخلیق و آغاز سے متعلق مفید نتیجوں پر پہنچنے کے لیے کافی ممدومعاون ہوسکتا ہے۔" (2)
پروفیسر شیرانی کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں:
"اردو اور پنجابی ان تمام لسانی مشابہتوں کے باوجود، جن کا ذکر مولانا محمود شیرانی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں کرتے ہیں، مزاج اور ساخت کے اعتبار سے مختلف زبانیں ہیں۔ ان میں اصلی اور نسلی امتیازات ہیں جو ان کے مختلف الاصل ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور صاف صاف چغلی کھاتے ہیں کہ یہ زبانیں ایک گھرانے کی نہیں دو گھرانوں کی ہیں۔ ایک نسل کی نہیں دو نسل کی ہیں۔" (3)
اردو کے آغاز کے متعلق پیش کیے گئے نظریوں کا جائزہ ڈاکٹر گیان چندجین نے اپنے ایک مضمون میں لیا ہے۔ میرامن، آزاد، نصیرالدین ہاشمی کے نظریوں کا ذکر کرنے کے بعد شیرانی کے نظریے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔
" محمود شیرانی کا نظریہ زیادہ قابل غور ہے۔ انہوں نے "پنجاب میں اردو" کے عرضِ حال میں لکھ دیا ہے کہ ان سے پہلے شیر علی خاں سرکوش نے اپنے تذکرہ اعجازسخن میں اردو کے آغاز کو سرزمین پنجاب سے منسوب کیا کسی نے اس تذکرے کو دیکھنے کی زحمت نہ کی بجز ڈاکٹر عبدالغفار شکیل کے۔ انہوں نے خبر دی کہ جو نظریہ شیرانی سے منسوب ہے دراصل ان سے پہلےاعجاز علی سرخوش بیان کرچکے تھے۔" (4)
شیرانی نے اس نظریہ کو مفصل اور مدلل پیش کرکے پایہ اعتبار کیا۔ ان کی پیش بہا تصنیف، 'پنجاب میں اردو' کے دیباچے میں ان کے نظریے کا خلاصہ ملتا ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ پروفیسر شیرانی اردو کے آغاز کے متعلق کیا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ
"ہم اردو کے آغاز کو شاجہان یا اکبر کے دربار اور لشکرگاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے عادی ہیں لیکن یہ زبان اس زمانہ سے بہت قدیم ہے بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انہی ایام سے ماننا ہوگا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں۔" (5)
اردو کے آغاز کے متعلق میرامن، سرسید، امام بخش صہبائی، محمد حسین آزاد وغیرہ کی آراء نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔
"یہ بیانات جو ہمارے تذکرہ نگار ایک دوسرے سے نقل کرتے آئے ہیں حقیقت سے بہت دور ہیں ہمیں ان کو صرف بزرگوں کے تبرک کےطور پر تسلیم کرنا چاہیے ورنہ کیا اکبر اور شاجہان سے پہلے دلی نہیں تھی یا ہندومسلمان نہ تھے یا لوگ سودا سلف نہیں لیتے تھے یا مختلف قومیں ایک ساتھ رہ سہہ کرکاروبار کرنا نہیں جانتی تھیں پھر اکبر شاجہان کے عہد کے ساتھ کیاخصوصیت ہے کہ اردو کی بنیاد رکھی جائے۔" اصل یہ ہے کہ اردو کی داغ بیل اسی دن سے پڑنی شروع ہوگئی ہے جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آکر توطن اختیار کرلیا ہے۔" (6)
پروفیسر شیرانی کی مذکورہ رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شوکت سبزواری اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں:
"مسلمان اہل علم نے اردو کا سنگ بنیاد دہلی میں رکھ کر اس کی نشوونما غوریوں کی عہد میں دکھایا اور شاجہان کے عہد میں پروان چڑھایا مولانا شیرانی پنجاب کو اس کا مولد بتاتے ہیں اور غزنویوں کے عہد میں اسے پھولتا پھلتا دکھاتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے۔ مولانا شیرانی عام مسلمان اہل علم کے خلاف اردو کی قدامت کے قائل ہیں وہ اس کے آغاز کو مغلوں یا خلجیوں سے پیچھے پلٹا کر غزنویوں کے عہد تک لے گئے۔(7)
پروفیسر شیرانی اردو کے آغاز کے متعلق مزید لکھتے ہیں:
"کہا جاتا ہے کہ مغربی ہندی جس کی برج بھاشا، ہریانی، راجستھانی، پنجابی اور اردو شاخیں ہیں قدیم پراکرت سوراسینی (شورسینی) کی یادگار ہے۔ لیکن جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے وہ نہ برج ہے نہ ہریانی اور نہ قنوجی ہے وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ ہمیں یہ تحقیق معلوم نہیں کہ جب مسلمان دہلی میں آباد ہوئے اس وقت اس علاقہ میں کیا زبان بولی جاتی تھی۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ دہلی کے قریب تین زبانوں یعنی ہریانوی، برج اور راجستھانی کا سنگم ہوتا ہے اور گریر سن نے تو صاف دہلی کو ہریانوی زبان کے علاقے میں شامل کردیا ہے مگر راقم کی رائے میں ہریانوی کوئی علیحدہ زبان کہلانے کی مستحق نہیں ہے بلکہ وہ پرانی اردو ہے یعنی وہی اردو ہے۔ جو گیارھویں صدی ہجری میں خود دہلی میں بھی بولی جاتی ہے۔ اس میں اور اردو میں بہت کم فرق ہے اگر ہم اس کو اردو نہ مانیں تو اردو کی شاخ ماننے میں تو ہمیں عذرنہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑےگا کہ یہ زبان اسلامی دور میں دہلی کے اثرات میں بنتی ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی آمد کے وقت کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ یا وہ راجستھانی ہوگی یا برج! اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کرکے جاتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ (8)
مندرجہ بالا اقتباس سے جو باتیں سامنےآتی ہیں وہ یہ ہیں:
۱۔ مغربی ہندی جس کی برج بھاشا،ہریانی، راجستھانی، پنجابی اور اردو شاخیں ہیں قدیم پراکرت شور سینی کی یاد گار ہے۔
۲۔ جس زبان سے اردو ارتقاپاتی ہے وہ نہ برج ہے نہ ہریانی اور نہ قنوجی ہے۔ وہ زبان ہے جوصرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔
۳۔ ہریانوی کوئی علیحدہ زبان کہلانے کی مستحق نہیں ہے بلکہ وہ پرانی اردو ہے یعنی وہی اردو ہے جو گیارھویں صدی ہجری میں خود دہلی میں بھی بولی جاتی تھی، اگر اس کو اردو نہ مانیں تو اردو کی شاخ ماننے میں تو ہمیں عذر نہیں ہونا چاہیے۔
۴۔ یہ زبان اسلامی دور میں دہلی کے اثرات میں بنتی ہے۔
۵۔ دہلی میں مسلمانوں کی آمد کے وقت راجستھانی بولی جاتی تھی یا برج؟
۶۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کرکے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لےکر گئے ہوں۔
مذکورہ بالا پہلی بات کے متعلق عرض کرنا ہے کہ مغربی ہندی کی شاخیں برج بھاشا، ہریانی، بندیلی، قنوجی، اور کھڑی بولی ہیں۔ نیز یہ کہ مغربی ہندی شورسینی اب بھرنش کی جانشین ہے اور شورسینی اب بھرنش، شورسینی پراکرت کی۔ راجستھانی اور پنجابی مغربی ہندی کی شاخیں نہیں ہیں البتہ یہ دونوں شورسینی اب بھرنش کی شاخیں ہیں کیونکہ شورسینی اب بھرنش سے ہی مغربی ہندی، راجستھانی پنجابی (مشرقی) وغیرہ زبانیں وجود میں آئیں۔ دوسری بات یہ تو درست ہے کہ جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے وہ نہ برج ہے نہ ہریانی اور نہ قنوجی، مگر یہ درست نہیں کہ اردو جس زبان سے ارتقا پاتی ہے وہ صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ خود ان کے اس بیان میں تضاد ہے جیسا کہ پوائنٹ نمبر ۶ سے ظاہر ہے یعنی اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کرکے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔
تیسری بات یہ کہ ہریانی اور نواح دہلی کی دوسری بولیاں برج، کھڑی وغیرہ مسلمانوں کی فتح دہلی کے بعد کا ارتقا ہیں اس لیے اس وقت تک نہ تو ہریانی کا مکمل ارتقا ہوا تھا اور نہ ہی اردو کا تو پھر ہریانی کو اردو کی شاخ کس طرح تصور کیا جاسکتا ہے۔
پروفیسر شیرانی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی آمد کے وقت کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ وہ راجستھانی ہوگی یا برج؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ نہ تو وہ راجستھانی ہے اور نہ ہی برج۔ بلکہ بقول پروفیسر مسعود حسین خان (9)
"اس عہد کی قدیم آپ بھرنش کی روایات میں جڑی ہوئی زبان ہے"
پروفیسر مسعود حسین خان مزید لکھتے ہیں (10)
"اپنے نظریے کی تائید میں شاید شیرانی کی سب سے کمزور دلیل یہی ہے کہ پنجابی مسلمانوں کی آمد سے قبل کے دوآبہ کے بالائی حصوں کی زبان برج بھاشا تھی، حالانکہ اس وقت تک برج کا ارتقا بھی پورے طور پر نہ ہوسکا تھا۔ اس کے ثبوت میں وہ فتح دہلی کے ساڑھے تین سو برس بعد کے دو مصنفوں (شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور مخدوم بہاء الدین) کی تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں۔
اب رہی یہ بات کہ یہ زبان اسلامی دور میں دہلی کے اثرات میں بنتی ہے اور یہ کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کرکے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ ان باتوں کے متعلق ڈاکٹر شوکت سبزوار رقمطراز ہیں۔ (11)
"اگر اسلامی دور میں دہلی کے اثرات میں بنی تو وہ بارہویں صدی عیسوی سے پہلے پنجاب میں کہاں پہنچ گئی اوراگر پنجاب سے ہجرت کرکے جاتی ہے تو وہ اردو نہیں پنجابی ہے۔"
یہاں ہمیں پھر یہ کہنا پڑے گا کہ مسلمان شورسینی اپ بھرنش اور اس کی عوامی شکل مغربی ہند بولتے ہوئے پنجاب سے دہلی گئے جس میں سے جدید ہند آریائی زبانوں کے بیچ پھوٹنا شروع ہوگئے تھے مگر ان کی نمایاں شکلیں سامنے نہیں آئی تھیں جو دہلی میں مسلمانوں کے اچھی طرح متمکن ہوجانے کے بعد ظہور پذیر ہوئیں۔
پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پروفیسر شیرانی کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے(12)
"پروفیسر شیرانی نے اپنی تصنیف 'پنجاب میں اردو' میں بعض تاریخی مفروضات کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کھڑی اور ہریانی پنجابی مسلمانوں کے داخلہ دہلی کے بعد ظہورپذیر ہوئی ہیں۔"
پروفیسر شیریانی کی کتاب (13) سے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں:
"چوتھی صدی کےاوآخر میں محمودی حملوں کا آغاز ہوتا ہے اور تمام پنجاب آلِ ناصر کے زیر اقتدار آجاتا ہے۔ آل غزنہ کی حکومت تقریباً ایک سو ستر سال تک رہتی ہے۔ اگر آل غزنہ سے پیشتر مسلمانوں کو کسی ہندی زبان کے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو اس عہد میں جو خاصا دراز ہے وہ پنجاب میں کوئی نہ کوئی زبان سرکاری، تجارتی و معاشرتی اغراض سے اختیار کرلیتے ہیں جن کو غوریوں کے عہد میں جب دارالسلطنت لاہور سے دہلی جاتا ہے۔ اسلامی فوجیں اور دوسرے پیشہ ور اپنے ساتھ دہلی لے جاتے ہیں دہلی میں یہ زبان برج اور دوسری زبانوں کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر وقتاً فوقتاً ترمیم قبول کرتی رہتی ہے اوررفتہ رفتہ اردو کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔"
مندرجہ بالا اقتباس کے متعلق صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ مسلمان پنجاب میں جو زبان اختیار کرتے ہیں اور جس کو اسلامی فوجیں اور دوسرے پیشہ وراپنے ساتھ دہلی لے جاتے ہیں وہ شور سینی اپ بھرنش اور اس کی عوامی شکل مغربی ہندی ہے جس میں سے جدید ہند آریائی زبانوں کے بیج پھوٹنا شروع ہوگئے تھے اس وقت تک برج بھاشا کا کوئی واضح روپ متعین نہیں ہوا تھا اس لیے یہ کہنا تو مناسب نہیں کہ برج کے اثرات سےترمیم ہوئی ہاں یہ کہنا درست ہے کہ اردو کی نمایاں شکل دہلی جاکرہی سامنےآئی پروفیسر مسعود حسین خان رقمطراز ہیں۔ (14)
"پنجاب پر غوریوں کے حملے ۱۱۶۸ء سےشروع ہوجاتے ہیں ۱۱۹۳ء میں بالآخر محمود غوری دہلی کے آخری ہندوسمراٹ پر تھوی راج کو شکستِ فاش دینے کے بعد دہلی اور اجمیر پر قابض ہوجاتا ہے۔ دہلی اس کے بعد ہندوستان کا دارالسلطنت قرار پاتا ہے۔ پروفیسر شیرانی نے لاہور سے دہلی کو پایہ تخت کے اس انتقال پر بہت زور دیا ہے حالانکہ یہ محمد تغلق کے انتقالِ پایہ تخت کی طرح نہ تھا جس نے دہلی اور اس کے اطراف کی بیشتر آبادی کو یک لخت گرم سفر ہوجانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور اس کے بعد بھی پنجاب کے صوبہ کا صدر رہا۔ اس لیے دہلی بسنے کے یہ معنی نہ تھے کہ لاہور اجاڑ دیا گیا تھا۔ تاریخ سے اس کی شہادت نہیں ملتی کہ لاہور کی آبادی نے کبھی بھی بڑے پیمانے پر دہلی کو ہجرت کی ہو۔ مسعود صاحب کایہ کہنا بالکل درست ہے کہ لاہور سے دہلی کو پایہ تخت کاانتقال محمد تغلق کے انتقالِ پایہ تخت کی طرح نہ تھا اوریہ بھی درست کہ دہلی بسنے کہ یہ معنی نہ تھے کہ لاہور اجاڑ دیا گے تھا مگر شیرانی کے مندرجہ ذیل بیانات بھی حقیقت پر مبنی نظر آتےہیں۔ (15)
"خطہ پنجاب کے باشندے اپنی قدوقامت اور طبعی جرات کی بناپرفوجی خدمات کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہیں اس لیے سلطان محمود نے جوفوج ہندووں سے انتخاب کی وہ تمام پنجابی تھی۔ اس کے جانشین بھی پنجابی فوجیں رکھتے تھے جب دہلی کی طرف مراجعت ہوئی ہے تو ایک بڑی تعداد پنجابیوں کی بھی تھی" جب معزالدین اور اس کے والی قطب الدین ایبک نے چند سال کے عرصے میں اجمیر،ہانسی،سرسستی، کہرام، میرٹھ، دہلی، بدایوں، قنوج، بنارس، مہروالاتھنیکر،گوالیر،کالنجر،اودھ اور مالوہ فتح کرلیےتو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس نئے علاقے کے انتظام کے لیے ان کو کس قدر آدمی درکار ہوئے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر شہر میں ان کو اپنی چھاؤنی رکھنی پڑی ہوگی۔ چاروں طرف طاقتور ہندوراجہ موجود تھے جن کو قدرتاً مسلمانوں سے عداوت تھی۔ اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان ایام میں شمال سے لوگ بڑی تعداد میں ہجرت کرکے ہندوستان کی طرف چلے گئے ہیں اور ہم قیاس کرسکتے ہیں کہ لاہور چونکہ پرانا دارالسلطنت تھا اس لیے ضروری ہوا کہ یہاں کے لوگ تبدیلی دارالسلطنت کے وقت بہ تقریب ملازمت وتجارت ودیگر خدمات زیادہ تعداد میں جائیں۔ قطب الدین ایبک کے ساتھ جو لوگ ہجرت کرکے دہلی آگئے ہیں اگرچہ یوں تو ان میں مختلف اقوام شامل تھیں مثلا ترک (جوبڑے عہدوں پر ممتاز تھے) خراسانی جو مناسب دیوانی پرسرفراز تھے۔ خلجی، افغان اور پنجابی لیکن ان میں زیادہ تعداد موخرالذکرکی تھی جو فوجی اور دیوانی خدمات کے علاوہ زندگی کے اورپیشوں پربھی متصرف تھے۔ اس سے قبل اشارہ کیا جاچکا ہے کہ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوں کے اختلاط سے اگر کوئی زبان نہیں بنی تو غزنوی دور میں جو ایک سوستر سال پر حاوی ہے ایسی مخلوط یابین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہوسکتی ہے ۔اردو چونکہ پنجاب میں بنی ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجود پنجابی کے مماثل ہو یا اس کے قریبی رشتے دار ہو۔ بہر حال قطب الدین کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کرسکیں اور ساتھ ہی ہندواقوام بھی اس کو سمجھ سکیں اور جس کو قیام پنجاب کے زمانے میں وہ بولتے رہے۔"
سرزمین پنجاب کے لسانی اثرات کو پروفیسر مسعود حسین خان بھی ماننے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔(16) "بازار اور لشکر میں نہ تو ترکی، فارسی کو دخل حاصل تھا اور نہ برج بھاشا کو۔ سلاطینِ دہلی کے ابتدائی عہد میں چونکہ فوج میں پنجابیوں کی کثیر تعداد تھی اس لیے سرزمین پنجاب کے لسانی اثرات حاوی تھے۔"
ایک اور اقتباس (17)
"اردو کی تہہ میں بنیادی بولی ہے اس کا تعلق تو نواحِ دہلی ہی سے ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ سلاطین دہلی کے عہد میں اس پر پنجاب کی زبان کا گہرا اثر رہا ہے۔ راجپوتوں کی دلی، ڈلی یا اپ بھرنش ادبیات کی "ڈھلی" ہریانہ کے علاقے میں تھی"۔
یہ بھی حقیقت ہے کہ ابتدائی سلاطین دہلی کے عہد کی حیثیت ایک فوجی چھاؤنی سے زیادہ نہیں تھی اور اسکا اعتراف مسعود صاحب نے بھی کیا ہے۔ لیکن مسعود صاحب نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ مسلمانوں کی فتح دہلی کے وقت جو لوگ (خواہ ان کی تعداد کچھ بھی رہی ہو) پنجاب سے مسلم حکمرانوں کے ساتھ دہلی گئے وہ کون سی زبان بولتے ہوئے گئے؟ دوسری بات یہ کہ خود ان کے کہنے کے مطابق چونکہ فوج میں پنجابیوں کی کثیر تعداد تھی اس لیے سرزمین پنجاب کے لسانی اثرات حاوی تھے۔ تیسری بات یہ کہ ابتدائی سلاطین دہلی کے عہد میں دہلی کی حیثیت ایک فوجی چھاؤنی سے زیادہ نہیں تھی اور جوہریانہ کے علاقے میں تھی تو پھر وہ کون سے حالات تھے جن کی بنا پر مسلم حکمرانوں کا قافلہ اس بات پر مجبور ہوا کہ وہ اپنی زبان چھوڑ کر دہلی کی زبان اختیار کرے۔(18)
مسلمان فاتحین جب پنجاب سے دہلی گئے تو ان کے فوجی اور دیگر متوسلین جو زبان بولتے ہوئے گئے وہ کوئی ایسی زبان شورسینی اب بھرنش اور اس کی جانشین مغربی ہندی تھی جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کرسکتی تھیں اور ساتھ ہی ہندو اقوام بھی اس کو سمجھ سکتی تھیں اور جس کو قیام پنجاب کے زمانے میں وہ بولتے رہے تھے۔
پروفیسر مسعود حسین خان کی کتاب سے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے پروفیسر شیرانی کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے سپردقلم کیا ہے فرماتے ہیں(19)
پروفیسر شیرانی نے پنجاب میں اردو لکھتے وقت اس لسانی حقیقت کو بالکل نظر انداز کردیا ہے کہ راجستھانی اور گجراتی کی طرح پنجابی کا تعلق بھی کسی زمانے میں زبانوں کی بیرونی شاخ سے تھا جس کے اثرات کی نشاندہی آج بھی کی جاسکتی ہے بعد کو اس پر اندرونی زبان کا اس قدر گہرا اثر پڑا کہ اس کی صورت بدل گئی۔"
مذکور بالا اعتراض کے متعلق صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جدید ہندآریائی زبانوں کی تقسیم کے سلسلے میں انہوں نے گریرسن کی اندرونی اور یبرونی تقسیم کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔
"چنانچہ ہمیں یہاں گریرسن سے اختلاف کرتے ہوئے چڑجی کی اس رائے سے متفق ہونا پڑتا ہے کہ اندرونی، بیرونی زبانوں کی یہ تقسیم لسانی اعتبار سے اتنی ہی مہمل ہے جتنی کہ تاریخ استدلال سے(20)
ایک اور جگہ بھی مزمدار کی تائید کرتے ہوئےلکھتا ہے(21)
"بی مزمدار کا خیال ہے کہ گریرسن ہندوستان کی قدیم زبانوں سےکماحقہ واقف نہ تھا اس لے لسانی فیصلے قول فیصل کا حکم نہیں رکھتے"۔
مسعودصاحب کہ یہ بات اپنی جگہ درست کہ گریرسن کے لسانیاتی فیصلے قول فیصل کا حکم نہیں رکھتے مگر سوال یہ پیداہوتا ہے کہ مسعود صاحب گریرسن کی اندرونی اور بیرونی زبانوں کی تقسیم کو مہمل بھی سمجھتے ہیں اور جگہ جگہ اس کی تائید بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخرایسا کیوں؟ اور گریرسن کی اندرونی اور بیرونی زبانوں کی تقسیم ہی مہمل ہے تو پھر مسعود صاحب نے جو اعتراض شیرانی پر کیا ہے وہ بھی مہمل ہے مسعود صاحب نے ڈاکٹر چڑجی کے لسانی نقشے میں تھوڑی سی ترمیم کرنے کے بعد ہندوستان کی جدید زبانوں کی گروہ بندی جس طرح کی ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مغربی ہندی مدھیہ دیش کی خاص زبان ہےاور پنجابی مدھیہ دیش کی زبان سے گہرا رشتہ رکھنے والی زبان۔ اس لیے ان دونوں میں بہت سی مشترکہ خصوصیات کا پایا جانا لازمی ہے جس کا اعتراف مسعود صاحب بھی کرنے پر مجبور ہیں۔
"قدیم دکنی اور پنجابی کے مذکورہ بنیادی اختلافات کے باوجود پروفیسر شیرانی کے اس دعویٰ میں کافی حد تک صداقت ملتی ہے کہ قدیم دکنی پنجابی کی مماثل ہے۔ (22)
اب ڈاکٹر شوکت سبزواری کے تین بیانات ملاحظہ فرمائیے۔
نمبر ایک: "یہ عجیب بات کہ اردو کی تائید کے بارے میں اردو میں دو نظریے بلند آہنگی کے ساتھ پیش ہوئے اور دونوں پنجاب سے، مولانا آزاد نے فرمایا، اردوبرج سے نکلی۔ اس کے مقابلے میں مولانا شیرانی کی آواز آئی، اردو پنجابی کی بیٹی ہے۔ (23)
نمبر دو: "اب تیسرے نظریےکو لیجیے کہ اردو پنجابی سے ماخوذ ہے مولانا شیرانی مرحوم کی قابل قدر کتاب "پنجاب میں اردو" کی اشاعت کے بعد سے یہ نظریہ زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ (24)
نمبر تین: "اردو اصلاً پنجابی ہے اس کا بڑا اور اہم سرمایہ پنجابی سے لیا گیا۔ یہ مولانا حافظ محمود خان شیرانی کا نظریہ ہے انہوں نے سب سےپہلے پنجابی اور اردو کی نسلی مشابہتیں دکھا کر یہ نتیجہ نکالا کہ اردو پنجابی سے ترقی پاکر وجود میں آئی۔ (25)
ڈاکٹر شوکت سبزواری کے مندرجہ بالا بیانات پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کیونکہ شیرانی نے ہر ہرگز نہیں کہا کہ اردو پنجابی کی بیٹی ہے اور نہ ہی یہ کہا کہ اردو پنجابی سے ماخوذ ہے۔شیرانی نے اردو اور پنجابی کی مشترکہ خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ (26)
"اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے اور جب سیانی ہوگئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے۔
آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسر شیرانی نے اردو کا آغازکا جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے اہم نکات یہ ہیں:
۱۔ اس کا وجود انہیں ایام سے ماننا ہوگا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں۔
۲۔ جس زبان سے اردو ارتقاء پاتی ہے وہ نہ برج ہے نہ ہریانی اور نہ قنوج ہے۔ وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔
۳۔ یہ زبان اسلامی دور میں دہلی کے اثرات میں بنتی ہے۔
۴۔ دہلی میں مسلمانوں کی آمد کے وقت راجستھانی بولی جاتی تھی یا برج۔
۵۔ اردو دہلی کے قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کرکے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔
۶۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو پنجابی کے مماثل ہو یا اس کی قریبی رشتہ دار ہو۔
۷۔ قطب الدین کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان اپنے ہمراہ لے کرروانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کرسکیں اور ساتھ ہی ہندو اقوام بھی اس کو سمجھ سکیں اور جس کو قیام پنجاب کے زمانے میں وہ بولتے رہے۔
۸۔ اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے۔ دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے اور جب سیانی ہوگئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے۔
ان متضادبیانات پر تفصیلی گفتگو کی جاچکی ہے۔ اس سب کو یہاں دہرانا ضروری نہیں البتہ مختصر طور پر اتنا کہہ دینا ضروری ہے کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اردو جس زبان سے ارتقا پاتی ہے وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زبان اسلامی دور میں دہلی کے اثرات میں بنتی ہے۔ تیسری جگہ کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں بنی اور وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ دہلی گئی۔ ان بیانات سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کا ذہن اس سلسلے میں واضح نہیں۔ اسی لیے متضاد باتیں ایک ساتھ کہہ رہے ہیں۔ دراصل ان کے پیش نظر اردو زبان کی حقیقت کا کھوج لگانا نہیں تھا بلکہ وہ اس کوشش میں تھے کہ پنجاب میں اردو زبان وادب کے ذخیرہ کو جمع کریں۔ اس کام کو کرتے کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ اردو کا مولد کچھ دوسرے علاقوں کو بتایا جارہا ہے تو انہوں نے بھی اپنی تحقیق میں سے زبان کا موازنہ پنجاب میں بولی جانے والی زبان سے کرنا شروع کیا، اردو اور پنجابی دونوں پر فارسی اور عربی کے اثرات موجود ہیں اور ذخیرہ الفاظ میں بیشتر حصہ اس لیے مماثلت رکھتا ہے کہ دونوں زبانوں نے یہ حصہ فارسی اورعربی سے لیا ہے۔ شیرانی صاحب اس نکتےکونہ سمجھ سکےاوراپنا سارا زورانہوں نے ان الفاظ کی مماثلت وقربت ثابت کرنے میں صرف کردی۔ اور بعد کے نام نہاد نقادوں نےعلم لسانیات کے سمجھے بغیر ان کے نظرئیے کی حمایت شروع کردی۔ اردو زبان اور پنجابی زبان کا ایک رشتہ موجود ہے کہ یہ دونوں زبانیں صدیوں سے ایک ہی خطے میں بولی جارہی یہں ۔اور ان دونوں زبانوں نے فارسی اور عربی کی توسط سے ایک دوسرے سے استفادہ بھی کیا ہے اور ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوئی ہیں۔ خصوصاً صوفیائے کرام نے جو زبان تبلیغ کے لیے استعمال کی وہ اردو اور پنجابی کی ملی جلی شکل تھی۔
اردو زبان پراکرتوں سے ترقی کرکے اپ بھرنشوں سے بننے والی اس زبان کی جدید شکل ہے جو پنجاب سے لے کر دہلی تک عوام بولتی تھی صوفیا و مبلغین نے اس بولی میں بیرونی اثرات یعنی فارسی اور عربی کے الفاظ اور تراکیب شامل کیے اور کئی صدیوں کے خراد پر اس کو سیچنے کے بعد موجودہ شکل دی جسے دربار اور شعراء نے شعوری کوشش سے جدید شکل دی۔ اس بولی کی خام صورت دکن میں دکھائی دیتی ہے پھر شمالی ہند میں خواص کی توجہ اورلکھنو میں درباروشعراء کی مسلسل محنت نے اسے ایک مکمل ادبی زبان کی صورت دی اور انگریزوں نے فارسی دشمنی کی بنا پر اس کی سرکاری سرپرستی کی اور اسے درسی کتابوں کی زبان بنادیا، یوں یہ بولی قرب و جوار کی دوسری بولیوں سے جن میں پنجابی بھی شامل ہے زیادہ ترقی کرتی چلی گئی اور آخر کار پورے خطے کی لینگوافرنیکا کی شکل اختیار کرگئی۔ اس حقیقت کو ماننے کی جگہ مختلف ادبی تاریخ نویسوں نے اس زبان کو اپنے خطے کی زبانوں سے منسوب کرنا شروع کیا۔ اور ان میں سب سے اہم نام حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ انہوں نے صرف اس بات کو بنیاد بنا کر کہ دہلی سے پہلے مسلمان افواج لاہور میں رہے اور وہاں سے دہلی گئے اس لیے اردو زبان دہلی سے پہلے لاہور میں بولی جاتی تھی اور لاہور کی زبان چونکہ پنجابی تھی اس لیے اردو زبان بھی پنجابی سے ماخوذ سمجھی جائے کا نعرہ لگایا اور ان کے جواب میں ہر خطے اور علاقے کے لوگوں نے اردو کو اپنے خطے کی زبان اور اپنی زبان سے ماخوذ قرار دینا شروع کردیا۔ یوں کسی نے کہا کہ اردو سندھی سے نکلی، کسی نے کہا کہ اردو گجراتی سےنکلی، کسی نے کہا کہ اردو کشمیری سے نکلی ہے، کسی نے کہا کہ اردو پشتوسے نکلی ہے اور کسی نی کہا کہ اردو ہندکو سے نکلی ہے۔ کیا ان سب کو یہ عالمگیر لسانی حقیقت معلوم نہیں تھی کہ کوئی بھی زبان کسی دوسری زبان سے نہیں نکلتی، اس کی ایک مکمل شکل موجود ہے البتہ زبانیں ایک دوسرے کو کچھ دینی اور کچھ لیتی ہیں۔ اس لیے زبانیں زندہ ہیں۔
حوالہ جات
۱۔ داستانِ زبان اردو ص ۸۷
۲۔ اردو کے آغاز کے نظریے گیان چند، (مضمون) مشولہ حقائق ص ۳۴۹۔۳۵۰
۳۔ پنجاب میں اردو ص۱۷
۴۔ ایضاً ص ۵۲۔۵۴
۵۔ داستان زبانِ اردو ص ۴۵
۶۔ پنجاب میں اردو ص ۱۸۔۱۹
۷۔ ایضاً ص ۱۷
۸۔ ایضاً ص ۵۲۔۵۴
۹۔ داستان زبانِ اردو ص ۴۵
۱۰۔ پنجاب میں اردو ص۱۸۔۱۹
۱۱۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو ص ۱۳۴
۱۲۔ ایضاً ص ۱۳۴
۱۳۔ داستان زبانِ اردو ص ۴۶
۱۴۔ کتاب مذکورہ ص ۲۳۴
۱۵۔ پنجاب میں اردو ص۱۳۰
۱۶۔ کتاب مذکورہ ص ۱۳۰
۱۷۔ پنجاب میں اردو ص۶۸۔۷۰
۱۸۔ کتاب مذکورہ ص ۱۴۴
۱۹۔ ایضاً ص ۱۴۰
۲۰۔ کتاب مذکورہ ص ۸۰۔۸۱
۲۱۔ اردو کے آغاز کے نظریے (مضمون) مشولہ حقائق ص ۳۴۷
۲۲۔ ایضاً ص ۳۴۸
۲۳۔ ایضاً ص ۳۴۵۔۳۴۶
۲۴۔ ایضاً ص ۳۶۰
۲۵۔ لکھنو کی لسانی خدمات ص ۱۳۳
۲۶۔ ڈاکٹر زور کی لسانی خدمات۔ مشمولہ لسانی مطالعے ص ۳۶۴