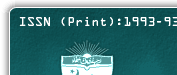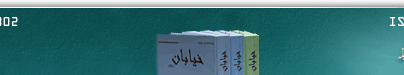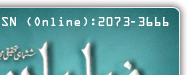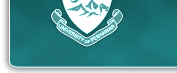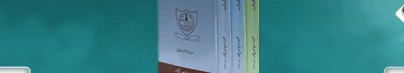اقبال کی اُردو غزلوں میں ردیف کا استعمال کی اہمیت
Abstract
This article expresses the importance of Radeef in Iqbal’s Urdu Ghazals. Radeef comes in the end of the verses of Ghazal. (In both lines of Matla and in second line of each verse). It plays a vital role not only in sizeable zing the main mood of Ghazal, but also making its rhythm more effective Iqbal’s like his other stylistic qualities uses Radeef in creative and poetic way. In his Ghazals Radeef has its own effect and distinguished value which makes the tempo and richness of thoughts. Author gives different examples from Iqbal’s Ghazals to support her point of view.
اقبال کی غزلوں خصوصاً "بالِ جبریل" کی غزلوں میں انہوں نے غیر مردف انداز اور رعایت کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس شعری مجموعہ میں ۷۷ غزلیات ہیں جن میں ۵۰ غیر مردف ہیں یعنی کل غزلوں کا قریباً ایک تہائی ردیف والی غزلیں ہیں اور دو تہائی ردیف کے بغیر۔
غزل گوئی کے باب میں اقبال کا یہ عمل ان کی فنکارانہ مہارت اور جدتِ اظہار کا آئینہ دار ہے۔ اُردو شاعری کی تاریخ میں غزل پر ایک دور ایسا بھی آیا جب بڑی لمبی لمبی ردیفین رکھنے کا رواج تھا۔ جرات انشاء اور ناسخ کے کلام میں ایسے بیسیوں نمونے مل جاتے ہیں جن میں ردیف نصف نصف مصرع کے برابر ہیں اور کہیں کہیں اس سے بھی بڑی۔ ایسی غزلوں میں اکثر اوقات ردیف کسی تخلیقی تجربے کا حصہ نہیں بنتی بلکہ وزن پورا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور بعض جگہوں پہ اس کا وجود بے کار معلوم ہوتا ہے۔
اقبال نے غزل کی موجودہ روایت میں آہستہ آہستہ آزادی حاصل کی وہ جس حد تک غزل کی ہیئتی اور صنفی پابندی کے اندر رہ کر آزاد ہوسکتے تھے ہوئے۔ انہیں یہ اندازِ غزل اس قدر پسند ہے کہ وہ اپنی نظموں کے اندر بھی اکثر ردیف کا استعمال کرتے "مسجد قرطبہ" اور "ذوق و شوق" کی نظمیں دیکھیے۔ یہ بندواربیت پر مشتمل ہیں مگر ان میں کسی بند کے اشعار ردیف میں نہیں جب کہ ٹیپ کے شعر جوہر بند کے اختتام پر ہیں ردیف وار ہیں۔ یہ قرینہ اور اہتمام آرٹ (Art ) کے ساتھ ساتھ مہارت (Craft ) کا بھی مظہر ہے ان نظموں کا پہلا پہلا بند ملاحظہ ہو۔
"مسجدِ قرطبہ"
سلسلئہ روز و شب، نقش گرِ حادثات
سلسلئہ روز و شب ، اصلِ حیات و ممات
سلسلئہ روز و شب، تارِ حریرِ دو رنگ
جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات
سلسلئہ روز و شب، سازِ ازل کی فغاں
جس سے دِکھاتی ہے ذات زِیروبمِ ممکنات
تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ
سلسلئہ روز و شب ، صَیر فیِ کائنات
تُو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار
موت ہے تیری برات، موت ہے میرے برات
تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا
ایک زمانے کی رَو جس میں نہ دن ہے نہ رات
آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہُنر
کارِ جہاں بے ثبات، کارِ جہاں بے ثبات (۱)
"ذوق و شوق" کے درج ذیل اشعار دیکھیے
قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں
چشمئہ آفتاب سے نُور کی ندّیاں رواں
حُسنِ ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود
دل کے لیے ہزار سُود ایک نگاہ کا زیاں
سُرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا سحابِ شب
کوہِ اضم کو دے گیا رنگ برنگ طَیلساں
گرد سے پاک ہے ہوا، برگِ نخیل دُھل گئے
ریگِ بُجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی طناب اُدھر
کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں (۲)
"مسجد قربطہ" کے پہلے بند میں حادثات، ممات، ممکنات، کائنات برات رات اور ثبات کے قوافی ہیں جب کہ ٹیپ کے شعر میں جہاں پہلا بند ختم ہوتا ہے ظاہر فنا، آخر فنا کے الفاظ ظاہر اور آخر قوافی اور فنا کی ردیف پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح "ذوق شوق" کے عنوان والی نظم کے پہلے بند میں سماں، رواں، زیاں، طیلساں، پرنیاں، کارواں کے قوافی پر اشعار ختم ہوتے ہیں جب کہ ٹیپ کا شعر "مقام ہے یہی اور دوام" کے قوافی کے ساتھ "ہے یہی" کی ردیف پر مشتمل ہے ان نظموں میں قوافی اور ردیف کے حسن کا جائزہ نظموں کے محاسن کے ذیل میں لیا جائے گا سرِ دست یہ بتانا مقصود ہے کہ اقبال نے غزل کی تنگنا ئےکے اندر ممکن حد تک آزادی حاصل کرلی تھی۔ غیر مردف غزلوں کی ۱۳ غزلوں میں ایک غزل بھی ردیف کے بغیر نہیں۔ دوسرے دور کی ۷ غزلوں کی بھی یہی صورت ہے۔ ان سب کی ردیفیں ہیں۔ تیسرے دور میں بھی ۸ غزلیں شامل ہیں جن سب کی ردیفیں ہیں یعنی "بانگ درا" کی سبھی غزلیات مردّف ہیں۔
اقبال نے اپنے اظہار کے اولین غزلیہ نمونوں میں ردیف کو برتا ہے مگر "بال جبریل" تک آتے آتے اقبال نے اظہارِ بیان میں ردیف کی پابندی کا اہتمام روا نہیں رکھا۔ فی الحال اس امر کا اظہار اور اس جدت بیان کی نشاندہی مطلوب ہے کہ اقبال اردو کے وہ پہلے معروف شاعر ہیں جنہوں نے بکثرت غیر مردف غزلیں لکھیں۔ اگر اردو شاعری کے ابتدائی نمونوں سے اقبال تک کے معاصرین کی غزل گوئی کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اقبال وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ غیر مردف غزلیں لکھیں۔ اس رجحان کے پس منظر میں اقبال کے ذہنی، نفسیاتی، تخلیقی جو عناصر بھی کار فرما ہوں ان کی غزل گوئی میں ردیف کی کلاسیکی گرفت اور روایتی جکڑ بندی سے آزاد ہونے کی طرف ایک غیر محسوس رویہ ضرور ملتا ہے۔ یہ رویہ اتنا نمایاں اور اہم ہے کہ علامہ اقبال کی مستعمل اصنافِ سخن کا جائزہ لیتے ہوئے غزل کے باب میں غیر مردّف غزلوں کا جائزہ سر فہرست جگہ بنا لیتا ہے۔
غیر مردّف غزلوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان میں ردیف کی پابندی نہ ہونے کے سبب اظہار میں آزادی اور کھلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر قوافی کے گرد اپنے احساسات، جذبات، خیالات اور مشاہدات کو جمع کرتا ہے اور کسی دوسری پابندی (ردیف) کے بغیر اپنا تخلیقی اظہار مکمل کر لیتا ہے۔ اقبال کے زمانے میں آزاد اور معرا نظم کا جو سلسلہ اپنی جڑیں پکڑ رہا تھا اقبال کو لاشعوری طور پر اس کا احساس ہور رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی غزل گوئی کے علاوہ زیادہ تر غزل گوئی غیر مردّف انداز میں کی۔
اقبال کی غزل گوئی کے بقایا اثاثے میں دو طرح کی غزلیں ملتی ہیں چھوٹی ردیف والی غزلیں، متوسط ردیف والی غزلیں اور نسبتاً ذرا لمبی ردیف والی غزلیں۔ چھوٹی، متوسط اور طویل ردیفوں کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ غزل کی بحریا وزن کی مناسبت سے ردیف مصرع کے کتنے صوتی حصہ پر مشتمل ہے یا مصرع کی صوتی اکائی میں کتنی جگہ گھیرتی ہے۔
بانگ درا کی غزلوں کے جائزہ سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔
یک لفظی ردیف
گلزار ہست وبود نہ بیگانہ وار دیکھ
ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ
(۳)
یک لفظی ردیف / دیکھ
دو لفظی ردیف نہ آتے ہیں ہمیں اس میں تکرار کیا تھی
مگر وعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی
(۴)
دو لفظی ردیف / کیا تھی
سہ لفظی ردیف کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا
اور اسیر حلقہ و دام ہوا کیوں کر ہوا
(۵)
سہ لفظی ردیف / کیوں کر ہوا
یہ مثالیں بانگ درا کی غزلیات حصہ اول کی ہیں ان کے علاوہ اس حصہ کی دوسری غزلیں بھی یک لفظی دو لفظی اور سہ لفظی ردیفوں پر مشتمل ہیں نمونتاً ایک ایک مصرع دیکھیے
عداوت ہے اسے سارے جہاں سے
(۶)
ردیف: سے
انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں
(۷)
جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں
(۸)
ردیف: میں
کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے
(۹)
ردیف: کرے
دو لفظی ردیف کی حامل غزلوں کے مصرعے
لاوں وہ تنکے کہیں سے آشیانے کے لیے
(۱۰)
ردیف: کے لیے
ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی
(۱۱)
ردیف: کرے کوئی
کہوں کیا آرزوئے بے دل مجھ کو کہاں تک ہے
(۱۲)
ردیف: تک ہے
ترے عشق کی انتہا چاہتا ہوں
(۱۳)
ردیف: چاہتا ہوں
سختیاں کرتا ہوں دل پر غیر سے غافل ہوں میں
(۱۴)
ردیف: ہوں میں
سہ لفظی ردیف کی حامل ایک غزل کا مصرع
مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑدے
(۱۵)
ردیف: بھی چھوڑ دے
حصہ اول "بانگِ درا" کی غزلیات کا ردیفوں کے حوالے سے گوشوارہ بنائیں تو درج ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں
یک لفظی ردیفیں : ۵
دو لفظی ردیفیں : ۶
سہ لفظی ردیفیں : ۲
ہر شعر میں ردیف کو قرینے کے ساتھ نبھایا اور کہیں بھی اس کا استعمال بوجھل یا ردیف برائے ردیف معلوم نہیں ہوا۔ اقبال کے ہاں اس غزل میں ردیف شعری انداز میں غزل کا حصہ بنتی نظر آتی ہے اور کسی شعر میں اس کے استعمال پر تضع یا بناوٹ کا گمان نہیں گزرتا اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طویل ردیف ہر جگہ اپنا فطری پن برقرار نہیں رکھ سکتی اور بڑے سے بڑے شاعروں کے ہاں بھی کہیں کہیں تکلف اور تضع کی حامل نظر آتی ہیں۔ اقبال کی غزل مختصر ہے۔ صرف چار شعروں کی۔ شاید اسی لیے اقبال نے اسے مہارت کے سات نبھایا ہے اور ہر شعر میں اس ردیف کا استعمال تخلیقی انداز میں ہوا ہے۔
مطلع کے علاوہ باقی شعر دیکھیے۔
گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر
شمع بولی، گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں
راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو
کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں
زائرانِ کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی
کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں
(۱۶)
حصہ دوم کی غزلیات میں ردیفوں کی تفصیل یوں ہے
یک لفظی
زمانہ دیکھے گا جب مرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا
(۱۷)
ردیف: کا
چمک تیری عیاں بجلی میں، آتش میں، شرارے میں
(۱۸)
ردیف: میں
دو لفظی
اک ذرا افسردگی تیرے تماشاوں میں تھی
(۱۹)
ردیف: میں تھی
مثالِ پر توِ مے طوفِ جام کرتے ہیں
(۲۰)
ردیف: کرتے ہیں
اسے ہے سودائے بخیہ کاری، مجھے سرِ پیرہن نہیں ہے
(۲۱)
ردیف: نہیں ہے
زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا
(۲۲)
ردیف: ہوگا
پنج لفظی
زندگی انساں کی اِک دم کے سوا کچھ بھی نہیں
(۲۳)
ردیف: کے سوا کچھ بھی نہیں
بانگ درا میں شامل کلام کا یہ حصہ اقبال کے قیام یورپ کے زمانے ۱۹۰۵۔ ۱۹۰۸ تک کا ہے اس دوران میں اقبال کی توجہ زیادہ تر نظموں کی طرف رہی۔ یہ سات غزلیں اس قیام کی یادگار ہیں ان کے فکری و فنی اوصاف سے قطع نظر ردیفوں کے حوالے سے اس حصہ غزل میں ایک پانچ لفظی ردیف قابل توجہ ہے۔ پورا مطلع یوں ہے
زندگی انساں کی اک دم کے سوا کچھ بھی نہیں
دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں
(۲۴)
اس طویل ردیف کا قبال نے غم، محرم اور زمزم کے قوافی کے ساتھ خوبصورتی سے نبھایا ہے "بانگِ درا" کے تیسرے حصہ میں غزلیات کی تعداد 8 ہے جس میں ردیفوں کا نقشہ یوں ہے۔
یہ سرود قُمری و بلبل فریب گوش ہے
(۲۵)
ردیف: ہے
نالہ ہے بلبلِ شوریدہ ترا خام ابھی
(۲۶)
ردیف: ابھی
پردہ چہرے سے اُٹھا، انجمن آرائی کر
(۲۷)
ردیف: کر
پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو
(۲۸)
ردیف: ہو
کبھی اے حقیقتِ منتظر! آ لباسِ مجاز میں
(۲۹)
ردیف: میں
جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی، نوائے زیر لب رہی
(۳۰)
ردیف: رہی
قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ
(۳۱)
ردیف: رکھ
دو لفظی ردیف
قبضے سے امت بے چاری کے دیں بھی گیا، دنیا بھی گئی
(۳۲)
ردیف: بھی گئی
"بانگِ درا" کی غزلیات کے تجزیاتی مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اقبال کے ہاں سوائے ایک پانچ لفظی ردیف کے زیادہ تر ردیفیں یک لفظی یا دو لفظی ہیں۔
غزلیاتِ بانگ درا میں ردیف کی کم سے کم شمولیت کا رجحان "بالِ جبریل" کی غزلوں میں ردیف کے بغیر غزل گوئی کے اسلوب کی بنیاد بنا۔ "بالِ جبریل" میں غیر مردّف غزلوں کا ایک قابلِ ذکر اثاثہ (۷۷ میں سے ۵۰) موجود ہے۔
"بالِ جبریل" کی ردیف والی غزلیں اس اعتبار سے اہم ہیں کہ اس میں مختصر، متوسطہ اور نسبتاً طویل ردیفوں کا استعمال اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ "بالِ جبریل" میں غزلوں کا وہ قابل ذکر اور قابل قدر فکری سرمایہ ہے جس کے ذریعے اقبال نے اپنے پیغام کو بہتر اور موثر پیرائے میں ادا کیا۔ "بانگِ درا" میں غزلیں نظموں کے قریباً برابر ہے۔ "بالِ جبریل" میں غزلیں ۲۶ (بہ شمول قطعہ غزلیہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے) ہیں اور نظمیں ۶۱ (بہ شمولہ قطعہ فطرت مری مانند نسیم سحری ہے اور کل اپنے مریدوں سے کہا پیرِ مغان نے)۔ یوں "بال جبریل" میں غزلوں کا اثاثہ ردیف کے مطالعہ کے حوالے سے زیادہ جاندار ہے۔ "بالِ جبریل" کی مردّف غزلوں میں ردیفیں "بانگِ درا" کے مقابلے میں کہیں زیادہ جاندار، با معنی اور پر تاثیر ہیں۔
عام ردیفوں (میں، کر، کا، نہیں، آخر، آیا) کے علاوہ اقبال کی غزلوں کی وہ ردیفیں ملاحظہ کیجئے جو اردو شاعری میں نہ صرف نئی ہیں بلکہ پوری غزل کے اجتماعی مزاج کو متعین کرنے میں بھی کارآمد اور موثر و بلیغ ثابت ہوتی ہیں۔
اگر کج روہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا؟
(۳۳)
ردیف: تیرا ہے یا میرا
پریشاں ہوکے میری خاک آخر دن نہ بن جائے
(۳۴)
ردیف: نہ بن جائے
دِگر گوں ہے جہاں، تاروں کی گردش تیز ہے ساقی
(۳۵)
ردیف: ہے ساقی
لاپھر اک بار وہی بادہ و جام اے ساقی!
(۳۶)
ردیف: اے ساقی
اپنی جولاں گاہ زیرِ آسماں سمجھا تھا میں
(۳۷)
ردیف: سمجھا تھا میں
عالم آب و خاک و باد، سرّ عیاں ہے تو کہ میں
(۳۸)
ردیف: ہے تو کہ میں
تو ابھی رہ گزر میں ہے، قیدِ سے گزر
(۳۹)
ردیف: سے گزر
دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے
(۴۰)
ردیف: نہیں ہے
عقل گو آستاں سے دور نہیں
(۴۱)
ردیف: سے دور نہیں
خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
(۴۲)
ردیف: سوا کچھ اور نہیں
نگاِہ فقر میں شان سکندری کیا ہے
(۴۳)
ردیف: کیا ہے
نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آسماں کے لیے
(۴۴)
ردیف: کے لیے
تو اے اسیر مِکاں! لا مکاں سے دور نہیں
(۴۵)
ردیف: سے دور نہیں
خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے
(۴۶)
ردیف: کیا ہے
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
(۴۷)
ردیف: اور بھی ہیں
مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے
(۴۸)
ردیف: بھی ہے
حادثہ وہ جوا بھی پردہ افلاک میں ہے
(۴۹)
ردیف: میں ہے
نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے
(۵۰)
ردیف: میں ہے
ردیف کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر شعر کے اندر اپنے جواز کا اظہار تخلیقی انداز میں کرے۔ اقبال کے اردو کلام میں "بالِ جبریل" کی غزلوں میں ردیفیں اس کمال مہارت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں کہ وہ ہر شعر میں معنویت کو آگے بڑھاتی اور مکمل کرتی نظر آتی ہیں اقبال کی اس غزل کو دیکھیے جس کا مطلع ہے
اگر کج رو ہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا
مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا؟ (۵۱)
اس غزل میں شاعر خدا تعالٰی سے مخاطب ہے "تیرا ہے یا میرا" کی ردیف اگرچہ استفہامیہ ہے اور استفہام بھی شاعر کے حوالہ سے انکاری ہے شعر کا مفہوم اپنے سیاق و سباق میں ظاہر کرتا ہے کہ کائنات کے اس نظام میں جو کچھ ہے اس کی ذمہ داری خدا تعالٰی پر ہے بندے پر نہیں۔ لہٰذا اسے بظاہر اس نظام میں کوئی نقص یا خرابی بھی نظر آئے تو وہ اس کے بارے میں فکر مند نہیں۔ مطلع کے بعد والے شعر دیکھیے
اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی
خطا کس کی ہے یارب! لامکاں تیرا ہے یا میرا؟
اُسے صبح ازل انکار کی جرات ہوئی کیوں کر
مجھ معلوم کیا، وہ راز داں تیرا ہے یا میرا؟
محمد بھی ترا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا
مگر یہ حرفِ شیرین ترجماں تیرا ہے یا میرا؟
اسی کو کب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن
زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا؟
(۵۲)
پانچ شعروں کی اس غزل میں آسماں، جہاں، لامکاں، رازداں، ترجماں اور زیاں کے ساتھ جہاں بھی تیرا ہے یا میرا ردیف آتی ہے اسی نے شعر کی معنویت اور رمزیت میں اضافہ کیا ہے۔ الگ الگ شعروں میں اپنے تخلیقی جواز کے ساتھ اس ردیف نے بحیثیت مجموعی غزل کی پوری فضا کو بھی مربوط کیا ہے ردیف کے استمعال کے باب میں یہ اقبال کی مہارت کا ثبوت ہے کہ ان کے ہاں ردیف بناوٹ تضع یا ردیف برائے کے ردیف نہیں بلکہ شعر کے نامیاتی وجود Organic System کا فطری حصہ بن جاتی ہے۔
اسی انداز کی دوسری ردیفوں نہ بن جائے ہے ساقی، اے ساقی، سمجھا تھا میں، ہے تو کہ میں، سے گزر، کے سوا کچھ اور نہیں وغیرہ میں ردیفوں کا استعمال بہت سلیقے سے ہوا ہے ایک معاون Supporting حیثیت میں ردیف قافیے کے ساتھ مل کر نہ صرف یہ کہ شعر کے مفہوم کو تخلیقی اور فطری انداز میں مکمل کرتی ہے بلکہ غزل کی مجموعی فضا کے حسن کو بھی نکھارتی ہے۔
اقبال کے ہاں بعض ردیفیں استفہامیہ انداز کی ہیں اور سوالات اٹھاتی نظر آتی ہیں مثلاً انہیں غزلوں میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے تیرا ہے میرا، کیا ہے، بھی ہے، تو ہے کہ میں وغیرہ کے مطالعے دیکھیے
اگر کج روہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا
مجھے فکرِ جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے میرا
(۵۳)
عالم آب و خاک وباد! سرِعیاں ہے تو کہ میں
وہ جو نظر سے ہے نہاں، اُس کا جہاں ہے تو کہ میں
(۵۴)
نگاہ فِقر میں شانِ سکندری کیا ہے
خراج کی جو گدا ہو، وہ قیصری کیا ہے!
(۵۵)
خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے
کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں، میری انتہا کیا ہے
(۵۶)
مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے ؟
خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے ؟
(۵۷)
ان غزلوں کے ہر شعر میں اقبال نے کوئی نہ کوئی سوال اٹھایا ہے یا استفہامیہ (انکاری) صورت میں بڑی بے بیزای سے اپنی مافی الضمیر کا اظہار کیا ہے خصوصا! نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے والی غزل میں خیالات اور افکار کا غالب رجحان کیا ہے کو کچھ نہیں کہ مفہوم سے عبارت کیا ہے۔
اس طرح اقبال کی ردیفوں میں بعض ردیفیں خطابیہ انداز لیے ہوئے ہیں خصوصاً "ہے ساقی" اور "اے ساقی" میں بیان و خطاب کا مرکز ساقی کی ذات ہے۔ اپنی علامتی حیثیت میں ساقی کہ فارسی اور غزل کا ایک اہم کردار ہے اپنے مفاہیم کی وسعت میں مجازی معنوں سے مرشد، خدا تعالٰی اور دوسری کئی عظیم ہستیوں سے نسبت رکھتا ہے۔ اقبال نے ان غزلوں میں بھی ردیف کا موثر اور پر معنی استعمال کیا ہے۔
"سمجھا تھا میں" "سے دُور نہیں" "کے سوا کچھ اور نہیں" کی نسبتاً ذرا بڑی اور "کے لئے" "نہیں ہے" "میں سے" کی ذرا چھوٹی ردیفیں بھی اپنے سیاق و سباق میں پر معنی اور موثر ہیں۔ پوری غزل کی فضا سازی میں معاون ہوتی ہوئی اپنے مفہوم کو بھی نکھار نظر آتی ہیں۔
یک لفظی ردیفوں میں اقبال نے آخر میں "کر" اور "نہیں" جیسے عام لفظوں کو بھی اپنی شعری شخصیت کے کمال سے موثر بنادیا ہے۔ "جواب" کے قافیے کے ساتھ آخر کی ردیف اجتماعی فضا پیدا کرکے غزل کو مثر بناتی ہے۔ اسی طرح پیام کے ساتھ "آیا" اور مقام کے قافیے کے ساتھ "سے گزر" کی چھوٹی سی ردیف کو اقبال نے اپنی مہارت فن کے ساتھ مافی الضمیر کے اظہار کے لیے خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ ان کے ہاں ردیفوں کا یہ قرینہ نہ صرف فطری اور تخلیقی انداز لیے ہوئے ہے بلکہ ہر جگہ غزل کی زمین سے بے ساختگی اور نامیاتی انداز میں ملتا ہے۔
حوالہ جات
۱۔ کلیاتِ اقبال، (اردو، اقبال اکادمی پاکستان لاہور، ۱۹۹۴ء، ص ۴۱۹، ۴۲۰۔
۲۔ کلیاتِ اقبال، ص ۴۳۸۔
۳۔ کلیات اقبال، ص ۱۲۴۔
۴۔ کلیات اقبال ص ۱۲۴۔
۵۔ کلیات اقبال، س ۱۲۶۔
۶۔ کلیات اقبال، ص ۱۲۵۔
۷۔ کلیات اقبال، ص ۱۲۷۔
۸۔ کلیات اقبال، ص ۱۲۸۔
۹۔ کلیات اقبال، ص ۱۳۱۔
۱۰۔ کلیات اقبال، ص ۱۲۵۔
۱۱۔ کلیات اقبال، ص ۱۲۸۔
۱۲۔ کلیات اقبال، ص ۱۲۸۔
۱۳۔ کلیات اقبال، ص ۱۳۱۔
۱۴۔ کلیات اقبال، ص ۱۳۲۔
۱۵۔ کلیات اقبال، ص ۱۳۳۔
۱۶۔ کلیات اردو، ص ۱۶۱۔
۱۷۔ کلیات اقبال، ص ۱۶۲۔
۱۸۔ کلیات اقبال، ص ۱۶۴۔
۱۹۔ کلیات اقبال، ص ۱۶۵۔
۲۰۔ کلیات اقبال، ص ۱۶۵۔
۲۱۔ کلیات اقبال، ص ۱۶۱۔
۲۲۔ کلیات اقبال، ص ۱۶۶۔
۲۳۔ کلیات اقبال، ص ۱۶۱۔
۲۴۔ کلیات اقبال، ص ۱۶۱۔
۲۵۔ کلیات اقبال، ص ۳۱۰۔
۲۶۔ کلیات اقبال، ص ۳۱۰۔
۲۷۔ کلیات اقبال، ص ۳۱۱۔
۲۸۔ کلیات اقبال، ص ۳۱۲۔
۲۹۔ کلیات اقبال، ص ۳۱۲۔
۳۰۔ کلیات اقبال، ص ۳۱۳۔
۳۱۔ کلیات اقبال، ص ۳۱۴۔
۳۲۔ کلیات اقبال، ص ۳۰۹۔
۳۳۔ کلیات اقبال، ص ۳۴۶۔
۳۴۔ کلیات اقبال، ص ۳۵۰۔
۳۵۔ کلیات اقبال، ص ۳۵۰۔
۳۶۔ کلیات اقبال، ص ۳۵۱۔
۳۷۔ کلیات اقبال، ص ۳۵۵۔
۳۸۔ کلیات اقبال، ص ۳۶۵۔
۳۹۔ کلیات اقبال، ص ۳۶۵۔
۴۰۔ کلیات اقبال، ص ۳۶۹۔
۴۱۔ کلیات اقبال، ص ۳۷۵۔
۴۲۔ کلیات اقبال، ص ۳۷۸۔
۴۳۔ کلیات اقبال، ص ۳۷۹۔
۴۴۔ کلیات اقبال، ص ۳۷۹۔
۴۵۔ کلیات اقبال، ص ۳۸۰۔
۴۶۔ کلیات اقبال، ص ۳۸۴۔
۴۷۔ کلیات اقبال، ص ۳۸۹۔
۴۸۔ کلیات اقبال، ص ۳۹۲۔
۴۹۔ کلیات اقبال، ص ۳۹۲۔
۵۰۔ کلیات اقبال، ص ۳۹۵۔
۵۱۔ کلیات اقبال، ص ۳۴۶۔
۵۲۔ کلیات اقبال، ص ۳۴۶۔
۵۳۔ کلیات اقبال، ص ۳۴۶۔
۵۴۔ کلیات اقبال، ص ۳۲۵۔
۵۵۔ کلیات اقبال، ص ۳۷۹۔
۵۶۔ کلیات اقبال، ص ۳۸۴۔
۵۷۔ کلیات اقبال، ص ۳۹۲۔