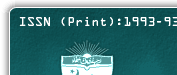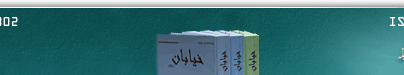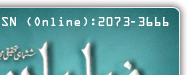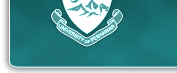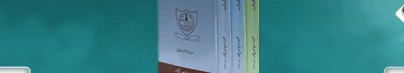"قدیم شعراء کے کلام کے لغات، وقت کی اہم ضرورت"
Abstract
Dictionaries, a dire need for every literary work, have been playing a vital role in literature since ages. They have greater importance than ever before now. Having realised this importance, dictionaries should be prepared about the work of earlier poets. This will surely be an important step towards saving our literary and cultural heritage. Mr. Nisar Ahmed has put his efforts in this direction and started working on a dictionary about Muhammad Quli Qutb Shah’s (1576—1611) poetry. He suggests that, as Urdu has emerged from different parts of Pakistan’s geographical boundaries so the dictionaries of work of early poet’s of Sindh, Punjab, NWFP, Balochistan and Northern areas of Pakistan should be prepared. He further suggests to prepare dictionaries with phonetic and phonological aspects of a word.
قدیم شعراء کا کلام یقیناً ایک عظیم ادبی سرمایہ اور ثقافتی ورثہ ہے۔ لیکن جب ہم اِس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اُس دور کی زبان اور اُس کے تلفّظ سے کامل واقفیت نہ ہونے کے سبب بہت دُشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اِس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم ان شعراء کے کلام کا صوتیاتی اور لسانیاتی مطالعہ کریں تو ہمیں اُردو زُبان کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہی نہیں بلکہ اُس دور کی معاشرت، طور طریق، لباس، گفتار، آداب و القاب اور عمومی ماحول کا اندازہ بھی ہوگا۔ جس طرح قدیم متون کو عام فہم بنانے کے لیے عصری تقاضوں کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ترتیب و تدوین کی جاتی ہے اُن پر حواشی لکھے جاتے ہیں، شرحیں لکھی جاتی ہیں اور تراجم کئے جاتے ہیں تاکہ وہ استفادے کے لیے کارآمد ہوجائیں۔ اِسی طرح جن شعراء کا کلام مدون ہوکر شایع ہو چکا ہے اُن میں سے کچھ کے لغات بھی مرتب ہوئے ہیں (مثلاً فرہنگِ نظیر(۱)، فرہنگِ اقبال (۲) وغیرہ) تاکہ اُن کے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہو، قدیم شعراء کے کلام کے لغات مرتب کرنا کوئی آسان کام نہیں، بقول مولوی عبدالحق:
"لغت میں ہر لفظ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کب کس طرح اور کس شکل میں اُردو زبان میں آیا۔ اور اس کے بعد سے اور اُس وقت سے تا حال اس کی شکل و صورت اور معانی میں کیا گیا تغیر ہوئے۔ اس کے کون کون سے معنی متروک ہوگئے اور کون کون سے اب تک باقی ہیں، اور اس میں اب تک کون کون سے نئے معنی پیدا ہوئے۔۔۔
ایسی لغت کا مرتب کرنا نہایت دشوار ہے، جب تک کافی سرمایہ، معقول عملہ اور بہت سے معاونین نہ ہوں اس کام کا انجام پانا ممکن نہیں، یہ نہایت محنت طلب اور سالہا سال کا کام ہے۔"(۳)
لغت نویس کو قدیم شعراء کی لغات مرتب کرنے کے لیے بڑے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چوں کہ اُسے بہت سے ایسے لفظ بھی ملیں گے جن کی نسبت پہ کہنا آسان نہ ہوگا کہ وہ متروک ہوچکے ہیں یا نہیں مثلاً: محمد قلی قطب شاہ کی ایک نظ "سالگرہ" (۴) کے اشعار ملاحظہ فرمائیے:
خدا کی رضا سوں برس گانٹھ آیا
سہیس شکر کرتوں برس گانٹھ آیا
نبی کی دعا ہے منڈپ سیس اوپر
اماماں دُعا سوں طناباں بندھایا (۵)
ان اشعار میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی آج بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مثلاً "برس گاٹھ"، "سالگرہ" کو کہتے ہیں۔
ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ کون سا لفظ متروک ہے اور کونسا مستعمل ہے۔ لیکن ہم "منثورات" کے مصنف سے متفق ہیں۔
"متروک الفاظ دوبارہ زندہ ہوجاتے ہیں اور لفظ کی زندگی او موت کا یہ کھیل ہر زندہ زبان میں جاری و ساری رہتا ہے۔ جب ہی تو ہم دیھکتے ہیں کہ کئی لفظ تیس چالیس سال متروک رہنے کے بعد اب پھر زبان میں داخل ہوگئے ہیں جیسے لفظ "سو" تیس چالیس برس تک متروک رہنے کے بعد اب اُردو میں داخل ہوگیا اور آج بھی مستعمل ہے"۔ (۶)
ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اُن الفاظ کو دوبارہ زندہ کیا جائے بلکہ علمی ضروریات کے تحت صرف یہ چاہتے ہیں کہ اُن الفاظ کے معنی و مفہوم کو واضح کیا جائے تاکہ ان قدیم شعراء کے کلام کا نہ صرف آسانی سے مطالعہ کیا جاسکے بلکہ آج کے شعری اور لِسانی مباحث اور مطالعے میں اِس کو شامل کیا جاسکے۔
یہ اَمر قابلِ تحسین ہے کہ پاکستان کی دیگر جامعات کی طرح شعبہ اُردو، سندھ یونیورسٹی جہاں راقم نا چیز نے ان کی تفصیلات شعبہ جاتی مجلّہ "تحقیق" (۷) میں پیش کی ہیں۔
مذکورہ ادبی تقاضوں کے پیشِ نظر راقم الحروف نے بھی "محمد قلی قطب شاہ" کے کلام کے فرہنگ (Glossary) کی تیاری کو اپنا مقصد بنایا ہے۔ (۸) یہاں بہ طور تعارف "محمد قلی قطب شاہ" سے متعلق چند معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔
"محمد قلی قطب شاہ" (۱۵۶۵ء تا ۱۶۱۱ء) اُردو کا پہلا صاحب دیوان اور پہلا عوامی شاعر ہے۔ خوش قسمتی سے اس کا ہزاروں اشعار پر مشتمل دفتر آج بھی ہماری دسترس میں ہے اِس نے معانی، ترکمان، قطب تین جدا گانہ تخلص کے تحت شاعری کی۔ اِس البیلے شاعر نے اُردو شاعری کی تقریباً ساری معروف اصنافِ سخن کو آزمودہ کاری کے لیے برتا۔ اس نے اپنے مخصوص لب و لہجے اور اپنی شخصیت کی چھاپ کے ساتھ نظمیں کہیں، قصیدے، مسدس، مخمس، رباعیات کہیں اس کی موضوعاتی نظمیں اِس کا نشانِ امتیاز ہیں۔ حالی، آزاد اور نظیر اکبر آبادی کو موضوعاتی شاعری کا باوا آدم سمجھا جاتا ہے ان سے لگ بھگ تین سو سال پہلے قلی قطب شاہ نے ایسے خشک موضوع پر نہ صرف قلم اُٹھایا بلکہ معمولی سنگ ریزوں کو گوہرِ نایاب بنا دیا۔
اِس قدیم صاحبِ دیوان شاعر پر سب سے پہلے ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے توجہ کی۔ اُنھوں نے ۱۹۴۰ء میں اِس شاعر کے ضخیم کلیات کی ترتیب و تدوین کی جسے سلسلہ یوسفیہ، حیدر آباد دکن نے شایع کیا۔(۹) اُس کے بعد ۱۹۵۸ء میں آپ ہی نے ایک مرتبہ پھر "نذیرِ محمد قلی قطب شاہ" کے عنوان سے کتاب مرتب کی۔ (۱۰) جس میں ہندوستان کے اُس وقت کے ماہرِ دکنیات کے تحریر کردہ مضامین کو یکجا کیا گیا۔ یہ کتاب ادارہ ادبیاتِ اُردو، حیدر آباد دکن سے شایع ہوئی۔ اس کے بعد وقار خلیل نے ۱۹۶۰ء میں "نذیرِ معانی" کے عنوان سے ایک کتاب شایع کی۔(۱۱) جس میں پہلی مرتبہ 'قلی قطب شاہ' اور اُس کے عہد کے متعلق قابلِ ذکر معلومات فراہم کی گئیں۔ اِس کے بعد محمد اکبرالدین نے ۱۹۷۲ء میں "قطب شاہ" کے کلام کا انتخاب مرتب کیا۔(۱۲) ان کتابوں کے بعد ماہنامہ "سب رَس" نے متعدد شماروں میں "محمد قلی قطب شاہ" سے متعلق مختلف موضوعات پر بکثرت مضامین شایع کئے۔(۱۳) اِس قدیم شاعر پر آخری قابلِ ذکر کام ڈاکٹر سیّدہ جعفر کا ہے اُنھوں نے کلیاتِ محمد قلی قطب شاہ کی ایک بار پھر ترتیب و تدوین کی اِن کایہ تحقیقی کام ۱۹۸۵ء میں منظرِ عام پر آیا۔(۱۴)
مذکورہ کام یقیناً "قلی قطب شاہ" کے فن کو سمجھنے میں معاون ہیں لیکن یہ سب کام چند لوگوں کا ہے جو بلاشبہ ماہرِ دکنیات ہیں اگر کوئی غیر دکنی طالب علم قلی قطب شاہ کو موضوع تحقیق بنانا چاہتا ہے تو اُس کے لیے سوائے "کلیات محمد قلی قطب شاہ" کے کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اور اس دور میں قلی قطب شاہ کا کلام سمجھنا بھی آسان نہیں۔ اس صورتِ حال میں قلی قطب شاہ کے کلام کے فرہنگ کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ چناں چہ راقم ناچیز نے فرہنگِ محمد قلی قطب شاہ کو ایک غیر دکنی طالبِ علم کی علمی ضرورت کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے مرتب کرنے کا بیڑا اُٹھایا ہے جس میں یہ کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے اُن الفاظ کو تحریر کیا جائے۔ جن کے معنی درکار ہیں۔ پھر یہ بتایا جائے کہ محمد قلی قطب شاہ نے اُن الفاظ کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اُس کے بعد یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کس زُبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد لفظ کی قواعدی حیثیت درج کی گئی ہے۔ جن الفاظ کے معنی کس لغت میں نہیں مل سکے اُنھیں دکنی بولنے اور جاننے والے فضلاء کرام سے دریافت کرکے لکھا گیا ہے۔ اور آخر میں سند کے طور پر "محمد قلی قطب شاہ" کے کلام سے شعر یا مصرع درج کیا گیا ہے۔
بلاشبہ فرہنگ کے مرتب ہوجانے سے کسی حد تک علمی و ادبی ضرورت پوری ہوجائے گی اور محمد قلی قطب شاہ پر تحقیق کے نت نئے موضوعات سامنے آئیں گے، خاص کر لسانیات سے دل چسپی رکھنے والے اسکالرز کے لیے موضوعات کا تعین آسان ہو جائے گا۔
یہ امر قابلِ تحسین ہے کہ لغت نویسی کی ضرورت و اہمیت کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے شعبہ اُردو سندھ یونیورسٹی نے پہلی مرتبہ (۲۰۰۶ء) لُغت نویسی کا پرچہ متعارف کرایا اس طرح کی کوئی نظیر، میری معلومات کے مطابق، برصغیر کی کسی اور جامعہ میں نہیں ملتی۔ شعبے کی بہت سی اوّلیات میں یہ بھی شامل ہے۔ لیکن پرچے کو نصاب میں شامل کرلینے سے اُس وقت تک مقصد پورا نہیں ہوگا جب تک طلباء سے عملی کام نہ کرائے جائیں۔ بڑی ضرورت یہ ہے کہ کم از کم ایم۔ اے کی سطح پر شاگردوں کو لغت نویسی کی طرف مائل کیا جائے۔
الغرض "لغت نویسی کے فن کو فروغ دینا عصری تقاضا ہے" اِس لیے کہ اُردو زبان اپنے نئے چولے کی طرف گامزن ہے۔ کیوں کہ یہ نئی جغرافیائی حدود میں داخل ہوچکی ہے اور اِس میں بہت سی زُبانوں کے بکثرت الفاظ شامل ہوچکے ہیں۔ اُردو زُبان اور اُس میں موجود مواد کو سائنٹفک انداز میں محفوظ کرنے اور اُسے موجودہ زمانے میں موضوعِ تحقیق بنانے کے لیے لغت نویسی ایک اہم طریقہ اور ضرورت ہے لہٰذا اِس فن پر خصوصی توجہ کی جانی چاہیے۔ اس بابت چند تجاویز ہیں جو قابلِ توجہ ہوسکتی ہیں۔
1۔ سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان اور شمالی علاقہ جات کے ابتدائی شعرائے اُردو کے کلام کے لغات مرتب کیے جائیں جو یقیناً ایک دل چسپ موضوع کی ابتدا ہوگی۔
2۔ لغت نویسی کے ساتھ ساتھ ایسے موضوعات کا انتخاب بھی کیا جائے جو زبان کے صوتی تجزیے پر مبنی ہوں چوں کہ ہر زبان میں آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے جن کے تلفظ میں نہایت سرعت کے ساتھ تبدیلی واقع ہوئی ہے۔
حواشی
۱۔ "فرہنگِ نظیر"، شریف احمد قریشی، فیض آباد، ٹانڈہ، ۱۹۹۱ء۔
۲۔ "فرہنگِ غالب"، امتیاز علی عرشی، رام پور، ۱۹۴۷ء۔
۳۔ "اُردو لغات اور لغت نویسی"، مولوی عبدالحق، مشمولہ اُردو لغت، جلد اوّل، مرتبہ: ابواللیث صدیقی، کراچی، اُردو بورڈ، ص "ہ"۔
۴۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ: مرتبہ: ڈاکٹر محی الدین قادری اُردو حیدر آباد، دکن، سلسلہ یوسفیہ، ۱۹۴۰ء، ص ۱۵۰ء ۱۵۱۔
۵۔ حضرت علی اور اُن کے گیارہ جانشینوں میں سے ہر ایک اور یہی بارہ امام یا ائمہ اثنا عشر کہلاتے ہیں۔
۶۔ "منثورات"، پنڈت برج موہن دتاتر یہ کیفی (دہلی فیض گنج دانش محل ۱۹۴۵ء) ص ۱۰۶۔ ۱۰۵، طبع اوّل۔
۷۔ شعبہ اُردو سندھ یونیورسٹی کے تحقیقی مقالات، مرتبہ: نثار احمد، "شعبہ جاتی مجلّہ تحقیق"، شمارہ ۱۴، سندھ یونیورسٹی جام شورو، ۲۰۰۶ء، ص ۱۳۲ تا ۱۷۹۔
۸۔ راقم شعبہ اُردو، سندھ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی رجسٹرڈ اسکالر ہے اور ڈاکٹر سیّد جاوید اقبال کی زیرِ نگرانی "فرہنگِ محمد قلی قطب شاہ مع حواشی و تعلیقات" کے موضوع پر تحقیقی کام کر رہا ہے۔
۹۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ: مرتبہ: ڈاکٹر محی الدین قادری زور، حیدر آباد دکن، سلسلہ یوسفیہ، ۱۹۴۰۔
۱۰۔ نذرِ محمد قلی قطب شاہ، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، حیدر آباد، ادارہ ادبیات اُردو، ۱۹۵۸۔
۱۱۔ نذرِ معانی، مرتبہ: وقار خلیل، ۱۹۶۰۔
۱۲۔ انتخابِ کلامِ محمد قلی قطب شاہ، مرتبہ: محمد اکبر الدین صدیقی، دہلی، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، ۱۹۷۲ء۔
۱۳۔ ماہنامہ "سب رس" حیدر آباد دکن، ادارہ ادیبات اردو شمارہ اپریل ۱۹۲۵ء، دسمبر ۱۹۴۲ء، جنوری ۱۹۵۲ء، فروری ۱۹۵۲ء، مارچ ۱۹۵۸ء، جنوری ۱۹۶۱ء، فروری ۱۹۷۶ء، مارچ ۱۹۷۶ء، مارچ ۱۹۷۷ء، مارچ ۱۹۷۸ء۔
۱۴۔ کلیاتِ محمد قلی قطب شاہ، مرتبہ: ڈاکٹر سیّدہ جعفر، نئی دہلی، ترقی اُردو بیورو، ۱۹۸۵ء۔
کتابیات
۱۔ "اُردو لغت"، جلد اوّل، کراچی، ترقی اُردو بورڈ، ۱۹۷۷ء۔
۲۔ زور، قادری، محی الدین، ڈاکٹر، "کلیاتِ سلطان محمد قلی قطب شاہ"، حیدر آباد، دکن، سلسلہ یوسفیہ، ۱۹۴۰ء۔
۳۔ زور، قادری، محی الدین، ڈاکٹر، نذرِ محمد قلی قطب شاہ، حیدر آباد، ادارہ ادبیات اُردو، ۱۹۵۸ء۔
۴۔ سیّدہ جعفر، ڈاکٹر، "کلیاتِ محمد قلی قطب شاہ"، نئی دہلی، ترقی اُردو بیورو، ۱۹۸۵ء۔
۵۔ "شعبہ جاتی مجلّہ تحقیق"، شمارہ ۱۴، سندھ یونیورسٹی جام شورو، ۲۰۰۶ء۔
۶۔ صدیقی، محمد اکبر، انتخابِ کلامِ محمد قلی قطب شاہ، دہلی، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، ۱۹۷۲ء۔
۷۔ عرشی، امتیاز علی، "فرہنگِ غالب"، رام پور، ۱۹۴۷ء۔
۸۔ قریشی، اکبر حسین، ڈاکٹر: "فرہنگِ فسانہ آزاد"، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۴ء۔
۹۔ قریشی، شریف احمد، "فرہنگِ نظیر"، فیض آباد، ٹانڈہ، ۱۹۹۱ء۔
۱۰۔ نسیم، امروہوی: "فرہنگِ اقبال، لاہور، اظہار سنز، ۱۹۸۴ء۔
۱۱۔ وقار خلیل، نذرِ معانی، حیدر آباد، ادارہ ادبیات، اُردو، ۱۹۶۰ء۔