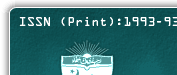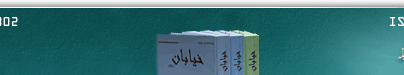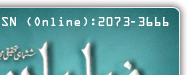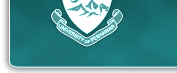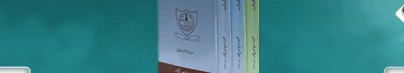محاورہ، روزمرہ، ضرب المثل اور تلمیح میں فکری اور معنوی ربط
Abstract
Every language has some components very particular to its culture. Its idioms, rozmarahs, proverbs and allusions are some of those components. But most of the linguists while referring to these components fail to distinguish them. They have some common features as well as some differences with respect to semantics and morphology. Abdullah Jan Abid has researched on the inter-relationship of idiom, rozmarah, proverb and allusion and found some similarities and distinctive features in order to give the readers a clear concept of these terms. Authentic definitions, relevant examples, easy language and comprehensiveness are the salient points of the article.
محاورہ اپنے معنوی اور فکری خدوخال میں زبان اور لسان کی مختلف اصطلاحوں کے معنوی پیکروں سے ہم آہنگ تو ہوتا ہے، لیکن ان کے مابین معنوی نظام کا بنیادی اخلاقی پہلو بہر حال موجود رہتا ہے۔ مثال کے طور پر محاورے، روز مرے، ضرب الامثال، تلمیحات اور تراکیب سازی کے عمل میں بعض رویے مشترک تو ہوسکتے ہیں، لیکن معنوی سطح پر اِن کے اندر باریک نکتے پنہاں ہوتے ہیں۔ یہ نکتے اِن کے معنوی مفہوم کے بنیادی اختلافی ڈھانچے کو رونما کرتے ہیں، جو اِن اصطلاحوں کے مابین معنوی سطح پر موجود ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ روزمرے، محاورے، تلمیح، تراکیب، ضرب الامثال وغیرہ کے مابین موجود اس باریک اور مہین فرق کو اجاگر نہیں کرتے اور ان تمام اصطلاحوں کو قریبی مفاہم میں استعمال کرتے ہیں۔
محاورہ کیا ہے؟ اور اِس کا روزمرے کے ساتھ کہاں تک معنوی تعلق، ربط اور رشتہ موجود ہے اور کہاں سے دونوں کے مابین اختلافی سرحدیں آغاز ہوتی ہیں، اُن کی نشاندہی دونوں کی تعریفوں کو اُن کے بنیادی مظاہر میں دیکھے بِنا ممکن نہیں ہوسکتی۔ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو اہلِ زبان کی رومرہ بول چال اور اُن کے مُرتّبہ یا ان کے مجوزہ قواعد کے مطابق ہوتا ہے۔ الفاظ کا یہ مجموعہ معنی میں استعمال ہوتاSpecialاپنے حقیقی، لغوی اور بنیادی معنوں کے بجائے اصطلاحی، غیر و ضعی اور
ہے اور اس میں مصدر کا ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔
دوسری طرف روزمرہ الفاظ کی ایک ایسی ترکیب کا نام ہے، جو دو یا دو سے زائد الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ روزمرہ اپنے حقیقی اور لغوی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں مصدر کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اس کی ترکیب بھی اہلِ زبان کی بول چال اور ان کے قواعد کے مطابق مرتب ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے لغوی معنی کے پسِ منظر سے جدا نہیں ہوتا۔ اِس پر کسی طرح کے اصطلاحی یا غیر حقیقی یا غیر وضعی مفہوم کا سایہ نہیں پڑتا۔ لہٰذا اِس کے اندر اپنے لغت اور بنیادی تھیم کے ساتھ ایک ایسا معنوی ارتباط پایا جاتا ہے، جو اِس کی فکر کو محاورے کی فکری حدود سے علیحدہ رکھتا ہے اور جہاں اِس کی شناخت محاورے کے معنوی منظر نامے سے علیحدہ سطح پر ممکن ہوسکتی ہے۔
روزمرہ محاورہ دونوں زبان کے ایسے اسالیب ہیں، جن میں زبان سانس لیتی ہے۔ زبان اور اس کی زندگی کا دارومدار جہاں دیگر تکنیکی اور فنی مظاہر سے وابستہ ہوتا ہے، وہاں زبان کی معنوی توسیع روزمرے اور محاورے کے بغیر، نہ تو ٹھوس تہذیبی اور فکری بنیادوں پر استوار رہ سکتی ہے اور نہ ہی زبان کا لسانی ارتقا ممکن ہوسکتا ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں اور اسالیب کسی بھی زبان میں اِسی نوعیت کا مفہوم رکھتے ہیں، جیسے جسم انسانی میں روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ روح کے بغیر کوئی جسم اپنی زندگی کا تصور نہیں کرسکتا۔ اِسی طرح کسی زبان کے ارتقا، اُس کی اشاعت اور ترویج کے ضمن میں روزمرے اور محاورے کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہوتا، جب روزمرے کے اسلوب میں دو یا دو سے ذائد الفاظ، جاودانی سطح پر ہم رشتہ ہو جائیں اور معانی کا ایک ایسا تنا ظر مرتب کریں، جہاں پر زندگی کی حقیقی رعنائیاں لفظوں کی اُس ترکیب یا مجموعے سے عکس انداز ہوں اور اِن کے مابین ایک فکری اشتراک اور ارتباط لغت کی معنویت کے ساتھ وابستہ ہو، تو روزمرہ اپنے مجموعی معنوی تناظر میں متشکل ہوتا ہے۔
محاورے کی طرح روزمرے کے اندر بھی کسی نوع کی معنوی یا لفظی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ اہلِ زبان کسی لفظ کو روزمرہ بول چال میں جس طرح سے بولتے ہیں، اُس لفظ یا لفظوں کے مجموعے کے ہم معنی یا مترادف الفاظ کو اُس مجموعے کے اندر رکھنے سے اس کے معنی کا وہ مروجہ نظام اور تسلسل ممکن نہیں رہ پاتا۔ مثال کے طور پر "انیس بیس" روزمرہ ہے۔ ہم اِسی پیٹرن پر، اسی انداز سے "بیس اکیس" کہہ کر روزمرے کا خون کردیتے ہیں یا "اٹھارہ انیس" کا فرق ہے۔ یہ "انیس بیس" کے فرق کو ہم "اٹھارہ اور بیس" یا "اٹھارہ اور انیس" یا "بیس اور ایکس" کے فرق سے نمایاں نہیں کر سکتے، کیونکہ شروع ہی سے اہلِ زبان اپنے قواعد کے مطابق اپنی روزمرہ بول چال میں، اِن الفاظ کے مجموعے کو اِس فکری رشتے اور ارتباط کے ساتھ بولتے چلے آ رہے ہیں۔ "پانچ سات" اردو کا روزمرہ ہے۔ اب یہ "پانچ سات"،"سات نو" نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ اس کے اندر صدیوں کے تسلسل اور لسانی عمل کے بعد جو ربط پیدا ہوا ہے، وہ ربط اہلِ زبان کے قواعد اور اُن کے روزمرہ استعمال کے مطابق ہے۔ اِس استعمال اور قواعد کے اندر تبدیلی کا درآنا، اِس اصطلاح اور اسلوب کی معنویت کو متاثر کرتا ہے۔ لہٰذا محاورے کی طرح روزمرے کے اندر بھی کسی نوعیت کی لفظی تبدیلی یا تغیر کو روا رکھنا جائز تصور کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں غلام ربانی رقم طراز ہیں: "روزمرہ میں اہلِ زبان کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس کے خلاف بولنا فصاحت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔" (ا)
اسی طرح شان الحق حقی نے روزمرے کی وضاحت کی ضمن میں لکھا ہے کہ:
"روزمرہ" وہ مخصوص کلمات ہیں، جو عموماً بولنے والوں کی زبان پر چڑھے ہوتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر چہ اجنبی کو اجنبی معلوم ہوں گے۔ مثلاً: آو دیکھانہ تاو" (لبلبی دبادی) وہ تو یہ کہے کہ (بندوق خالی تھی ورنہ بیٹھے بٹائے کسی کا خون ہو جاتا) خدا بری گھڑی سے بچائے، سچ پوچھو تو (مجھے ان کی یہ حرکتیں) ایک آنکھ سے نہیں بھاتیں۔ چلو خیر، وہ جانے ان کا کام جانے" اس عبارت میں، جو ٹکڑے قوسیں سے باہر ہیں۔ روزمرہ کی ذیل میں آتے ہیں۔" (۲)
محاورے اور روزمرے میں الفاظ کی جو ترتیب ابتدا سے مرتب ہوچکی ہے، اُس میں کسی لفظ کو اس کی جگہ سے دوسرے مقام پر منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ لفظوں کے آگے پیچھے کرنے سے نہ محاورہ، محاورہ رہ سکتا ہے اور نہ روزمرہ، روزمرہ، کیونکہ زبان کے ارتقائی عمل کے مابین جب کسی محاورے یا روزمرے کی تشکیل اور ترکیب ہوتی ہے۔ تو جو لفظ جہاں موجود ہوتا ہے، صدیوں تک اُس کا محاورے یا روزمرے میں وہی پیٹرن، صورت اور ہیئت موجود رہتی ہے۔ (محاورے اور روزمرے) کے لفظوں میں کسی نوعیت کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ لفظوں کے اندر تغیرات کی عدم موجودگی اُس کی معنوی کیفیت کو ہم آہنگ رکھتی ہے اور اِسی لیے صدیوں کے سفر اور زمانے کے بدلتے ہوئے تناظر کے باوجود، اس میں معنوی سطح پر بھی کسی نوعیت کی تبدیلی کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔
ماہرین نے روزمرے اور محاورے کے مابین فرق اور اختلاف کی بنیادی وجہ ان کے معنوں میں حقیقی غیر حقیقی فرق کو بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ حالانکہ دونوں کے مابین ایک بنیادی اختلاف مصدر کے علامتی حرف "نا" ( اُردو میں) اور اسی طرح دنیا کی دوسری زبان میں جو علامتِ مصدر ہے، وہ اس اختلافی معنویت کو آشکار کرنی ہے۔ علامتِ مصدر وہ بنیادی اختلاف ہے جو محاورے اور روزمرے کے مابین وقوع پذیر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی محاورہ ایسا نہیں ہوتا، جو علامتِ مصدر نہ رکھتا ہو اور یہ ایک ایسی علامت ہے، جو محاورے کو روزمرے سے علیحدہ اور منفرد حیثیت عطا کرتی ہے۔ دونوں کے مابین لفظی تغیرات میں امتیازی وصف محاورے میں موجود حرفِ مصدر یا علامتِ مصدر کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ محاورے اور روزمرے کے درمیان دوسری تفاوت جو معنوی سطح پر رونما ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ محاورے میں الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ اپنے غیر حقیقی یا اصلاحی معنویت میں مستعمل ہوتا ہے، جبکہ روزمرے میں اس کے الفاظ کی جو ترکیب معنویت مرتب اور متعین ہوتی ہے، وہ لغت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ روزمرے میں بے معنی یا مہمل الفاظ بھی وارد ہوتے ہیں،جبکہ محاورے میں مہمل یا بے معنی الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ موجود نہیں ہوتا۔ ہر لفظ ایک معنوی پیکر ہوتا ہے، وہ کسی خاص معنوی مفہوم کو اجاگر کرتا ہے اور اُس محاورے کے تناظر میں ڈھل کر کسی مخصوص معنویت کا حامل بن جاتا ہے جو محاورے کے معنوی قرینے کو ایک تناظر عطا کرتی ہے۔
روزمرے اور محاورے کی طرح لسانیاتی قواعد کی کچھ دیگر اصطلاحیں بھی محاورے کے ساتھ معنوی اشتراک رکھتی ہیں اور کچھ معنوی اختلاف کی حامل بھی ٹھہرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ضرب المثل اور کہاوت دو ایسی اصطلاحیں ہیں، جن کو اکثر و بیشتر لسانیات کی کتابوں میں محاورے کا مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جیسے محاورہ، روزمرے کے مقابلے میں ایک علیحدہ معنویت، اپنے ظاہری خدوخال میں مختلف پیکر اور معنوی سطح پر اپنی داخلی مظاہر میں معنی کی ایک بالکل منفرد اور نئی دنیا کا حامل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ضرب المثل اور محاورے کے مابین بھی کہٰن لفظ کا معنوی اشتراک موجود بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اِن اصطلاحوں کے مابین ایک ایسا باریک معنوی اختلاف موجود ہوتا ہے۔ جو اِن تراکیب اور اصطلاحوں کو اپنے اپنے معنی کے خدوخال متین کرنے میں معاون ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ان کو مختلف معنوی ماحول میں دریافت کرتا ہے۔
ضرب المثل عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے مترادفات دنیا کی دوسری زبانوں میں بولے جاتے ہیں۔ اُردو زبان میں ضرب المثل، اکھان اور کہاوت ایک دوسرے کے مترادف ہم معنی اصطلاح کے طور پر مروج ہیں، جبکہ پشتو میں اس کے لیے "متل" کی اصطلاح مروج ہے۔ ضرب المثل لفظوں کا وہ مجموعہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کے تجربات، ان کے فکری یا معنوی احساسات، ان کی زندگی میں گزرنے والے واقعات یا ان کی زندگی میں رونما ہونے والے اُن سانحات کی کہانی کو دو یا دو سے زائد الفاظ کے ایک ایسے ترکیب ماحول میں مرتب کرتے ہیں، جس میں مصدر یا افعال کی تجربات اور مشاہدات کے تخلیقی آہنگ سے مرتب ہوکر صدیوں کا سفر کرتے ہوئی ہماری تہذیبی، فکری اور لسانی زندگی کا ایسا لازمہ قرار پاتی ہے، جس کے اندر ہمیں عوامی ذہانت اور اسلاف کی زندگیوں کے وہ دانشمندانہ رویے دکھائی دیتے ہیں کہ اُس سے کہاوت، ضرب المثل یا "متل" اپنا تخلیقی اظہار پاتی ہے۔ اس ضمن میں شان الحق حقی رقم طراز ہیں کہ:
"ضرب الامثال عوامی سطح پر پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں عوامی فطانت سمائی ہوتی ہے اور عوامی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ پھر خواص بھی ان ہی مثلوں اور کہاوتوں کو برتتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اکثران کے اپنے ماحول یا معاشرے سے تعلق نہیں رکھیتں۔ نہ صرف امثال بلکہ الفاظ، تلفظ، محاورے وغیرہ کے معاملے میں بھی عوام کے آگے خواص کی زیادہ نہیں چلنے پاتی۔" (۳)
اور افتخار عارف کے مطابق:
"ضرب الامثال بالعموم عوامی ذہانت کی امین ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے صدیوں کی دانش کارفرما ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں زبان کی زینت اور زیور تصور کیا جاتا ہے اور تحریر و تقریر میں رنگا رنگی اور ندرت پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔" (۴)
محاورے اور ضرب المثل میں جو مشترک آہنگ پایا جاتا ہے، وہ اُس دانش، حکمت، دانائی یا اس ذہنی اور فکری استعداد کا وہ قرینہ ہے، جو زندگی کے تجربے سے پھوٹتا ہے، لیکن مختلف صورتیں اور شکلیں اوڑھنے کے بعد یہ ایسی ترکیبی صورتیں اختیار کرتا ہے کہ زبان کے اصطلاحی پیکر میں اُس کا نیا آہنگ یا نیا نام سامنے آتا ہے۔ ضرب المثل ہو یا محاورہ اس میں ہمارے بزرگوں کے تجربات، زندگی کی دانش کے ساخت باہم آمیخت ہوکر ان کے مشاہدے اور تجربے کو ایک ایسی ترکیب صورت میں اجاگر کرتے ہیں، جو کہیں کہاوت کا نام پاتی ہے اور کہیں اُس دانائی اور حکمت کو محاورے کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں اصطلاحوں کے مابیں جو ربط اور علاقہ موجود ہے، وہ دانش، زندگی کے تجربے یا مشاہدے سے مستعار وہ روح اور فکر نچوڑ ہے۔ جو صدیوں پہلے اسلاف نے اپنے تجربات کی روشنی میں الفاظ کے پیکر میں متشکل کیا تھا لیکن اب انہیں جو صورتیں میسر آئی ہیں، وہ ان کے معنوی خدوخال، اصطلاحی رویوں اور ظاہری ناموں کو متشکل کرتی ہیں۔ اگر کوئی ترکیب، مصدر، علامتِ مصدر، افعال اور اس کی مختلف صورتوں کے ساتھ وضع ہوتی ہے، تو وہ محاورہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنی میں مستعمل ہو، جبکہ ضرب المثل لفظوں کا وہ مجموعہ ہے، جو اسلاف کی زندگی کے دانشمندانہ تجربے، مشاہدے اور رویے اور تجربے سے مستفید ہوتا ہے اور اس میں زندگی کی حقیقی رعنائی کا ایک ایسا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، جو نفسیاتی، سماجی، فکری، تہذیبی، تاریخی اور انسانی تجربات اور اِس پر رونما ہونے والے مذہبی مظاہر اور رویوں سے متشکل ہوتا ہے۔
محاورے اور کہاوت میں جو مشترک رویہ بنیادی طور پر سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کے پیچھے اسلاف کا کوئی دانشمندانہ رویہ، زندگی کا کوئی تجربہ، مشاہدہ اور پہلو متشکل ہوتا ہے۔ جو آنے والی نسلوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا مینارہ نور بن سکتا ہے اور جس کے پیچھے انسان یا انسانوں کی ایک جماعت کا تجربہ، گہرے مشاہدے اور ان کی فکری معنویت کے جِلو میں سامنے آتا ہے۔ کہاوت لفظوں کی ایسی ترکیب کا نام ہے، جس میں ایک پورا جملہ موجود ہوتا ہے۔ محاوہر جملہ نہیں ہوتا وہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جو عام صورتوں میں علامتِ مصدر پر ختم ہوتا ہے اور اس مصدر کی پوری گردن ممکن ہوتی ہے۔ مثلاً غم کھانا، وہ غم کھاتا ہے، دہ غم کھا رہا ہے، وہ غم کھائے گا وغیرہ، جبکہ ضرب الامثال میں گردان کی اجازت نہیں ہوتی۔ ضرب المثل اپنے اندر پوری معنویت رکھتی ہے، وہ مرکبِ تام اور مرکبِ مفید ہوتا ہے، وہ ایک ایسا مکمل جملہ ہوتا ہے، جس کے اندر اس جملے کی تمام معنویت متشکل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سیفی پریمی نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:
"اصل میں ضرب المثل ایک جملہ تامہ ہوتا ہے اور اپنا ذاتی مفہوم ادا کرنے کے لیے کسی دوسرے جملے یا عبارت کا محتاج نہیں ہوتا۔" (۵)
محاورہ جملہ نہیں ہوتا، یہ اپنی ذات میں اپنے معنی کی کشید میں تو معاونت کرتا ہے، لیکن کسی بھی رویے اور حوالے سے پوری کیفیت کو سامنے نہیں لاتا۔ محاورہ ہر زبان کا ایک لازمی جزو ہوا کرتا ہے۔
محاورہ زبان کے مختلف استعمالات میں اپنی افعالی صورتوں کو بدلتا رہتا ہے یعنی جملے میں استعمال کرنے سے محاورے کی علامتِ مصدر، جملے کی مناسبت کے ساتھ افعال اور اس کی صورتیں تبدیل کرتی ہیں، جبکہ کہاوت کو جب آپ اس کے رویوں میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ کسی طور بھی لفظی تغیر و تبدل قبول نہیں کرتی۔ اگر آپ اس میں کسی نوعیت کی توڑ پھوڑ یا شکست و ریخت کے عمل کو روا رکھتے ہیں، تو اُس کی ساری معنویت توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے اور یہ ٹوٹ پھوٹ اِس کے داخلی اور خارجی نظام کو اس کی معنویت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ لہٰذا زبان اور زبان کے استعمالات میں کہاوت کو من و عن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی طرح کے لفظی تغیر و تبدل کو دخل حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے تو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے یہ لکھا ہے کہ:
"محاورہ کلام کا جز بن کر اس میں جزب ہو جاتا ہے۔ کہاوت میں یہ قابلیت نہیں ہے۔"(۶)
محاورے اور ضرب المثل میں بنیادی طور پر خاصا فرق پایا جاتا ہے، تاہم بعض محاورات اور ضرب الامثال ایسی ہیں، جن میں لفظی سطح پر سوائے مصدر کے کسی طرح کی کوئی تبدیلی رونما ہوتی دکھائی دیتی۔ مثلاً پشتو میں ایک محاورہ ہے، "د پیخے نھ تیختھ کول" آئی (بلا) سے بھاگ جانا) "د پیخے نھ تیختھ نشتھ" ضرب المثل ہے، لیکن اس سے "نشتہ" (نہیں) کو ہٹا کر "کول" ڈالنے سے (جو مصدر ہے) محاورہ بن جاتا ہے، اس مصدر نے محاورے اور کہاوت یا ضرب المثل کے اندر بنیادی حدِ فاصل یا اختلافی لکیرھی کھینچ دی ہے۔ بعض کہاوتیں محاورہ ہوسکتی ہیں، لیکن اس میں مصدر کی شمولیت بنیادی شرط ہے۔ اگر کہاوت میں مصدر شامل ہے تو وہ کہاوت نہیں ہے، بلکہ محاورہ ہے اور بعض محاورات سے اگر علامتِ مصدر کو حذف کردیا جائے تو جو باقی رہ جاتی ہے، وہ کہاوت ہوتی ہے، محاورہ نہیں ہوتا۔
تلمیح بھی ایک ایسی ترکیب کا نام ہے جو ایک، دو یا دو سے زائد لفظوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اُن دو یا دو سے زائد لفظوں کے تناظر یا پسِ منظر میں کوئی تاریخی واقعہ، کردار کوئی سانحہ یا رسم رواج مذکورہ ہوتا ہے۔ ایک دو لفظوں کے بولنے یا سن لینے سے وہ تاریخی یا نیم تاریخی واقعہ جو تاریخ کے کسی قدیم زمانے میں، کسی شخصیت یا کسی رسم رواج سے متعلق ہوتا ہے، فوراً ہماری نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے۔ تلمیح دراصل ہمارے بزرگوں کے قدموں کے وہ نشان ہیں، جن پر ہم اُلٹے قدم چلتے ہوئے، اُس واقعے تک پہنچ جاتے ہیں۔ زبان میں تلمیح کی اہمیت بہت بنیادی ہوتی ہے۔ ہر زبان کی تلمیحات اس زبان کی تہذیب، ماضی، کلچر اور اس کی قوم کے اسلاف کی زندگیوں سے پھوٹتی ہیں۔ مولوی وحید الدین سلیم کے نزدیک:
"اگر کسی زبان کی تلمیحات بغور مطالعہ کی جائیں، تو ان سے اس زبان کے بولنے والوں کے گذشتہ واقعات اور تاریخ پرروشنی پڑتی ہے۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کے اوہام، ان کے معاشرتی حالات اور ان کی رسوم اور مشاغل معلوم ہوتے ہیں۔ کسی قوم نے جس طرح تمدنی منزلیں رفتہ رفتہ طے کی ہیں اور جو تبدیلیاں اس کی زندگی میں یکے بعد دیگرے ہوتی رہی ہیں، اس کی زبان کی تلمیحات کے مطالعہ سب نظر کے سامنے آجاتی ہیں۔"(۷)
تلمیح اور محاورے میں معنوی ربط اور علاقہ تو موجود ہوتا ہے کہ دونوں کے پسِ منظر میں کوئی واقعہ، سانحہ، کوئی حکمت اور دانائی کی بات یا کوئی رسم و رواج اور طرزِ زندگی کا کوئی پہلو یا کوئی مذہبی قصہ یا کوئی متھ یاد یو مالائی صورت موجود ہوتی ہے، لیکن دونوں کا خارجی پیکر یا پیٹرن ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تلمیح اور محاورے کو ان کے ظاہری اور خارجی پیکر یا اوصاف کی بنا پر کھبی موجود ہو سکتا ہے یعنی کوئی محاورہCombinationبآسانی علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ دونوں کے درمیان
تلمیح محاورہ بھی ہوسکتی ہے، لیکن دونوں اپنے اپنے معنوی پس منظر ایک ہونے کے باوجود دونوں ایک نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں اصلاحیں مختلف ہیں اور دونوں اپنے اپنے معنوی دائرہ ہائے کار مرتبہ کرتی ہیں۔ دونوں کا ایک علیحدہ علیحدہ خارجی پیکر ہے، لیکن جو چیزیں محاورے کے لیے لازمی ہوتی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کی جو ترکیب ہوتی ہے اور ان کا جو معنوی آہنگ ہوتا ہے، وہ مجازی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اہلِ زبان کے قواعد کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ تلمیح کے لیے اُس زبان کے قواعد کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ وہ دوسری زبان سے سفر کرتی آتی ہے۔ مثلاً اُردو، پنجابی، سندھی بلوچی یا پاکستان کی دیگر زبانوں میں تلمیحات کا جو نظام ہے، وہ عربی عجمی معاشرے سے مسلمانوں کے ساتھ سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ پشتون تہذیب اور زبان کی زیادہ تر تلمیحات عربی اور فارسی کی وساطت سے پشتو میں مروج ہوئیں۔ اسی طرح اُردو اور پاکستان کی دیگر زبانوں میں بھی تلمیح کا فکری تناظر اسی طرح مرتب ہوتا ہے، لیکن محاورے میں دوسری زبانوں سے اخذ و استفادے کے باوجود ہر زبان کا اپنا ایک فکری کینوس ہوتا ہے، جس پر وہ زبان قوم یا تہذیب جس سے وہ محاورہ متعلق ہوتا ہے، ان کی زندگی کے مختلف رنگوں کو اپنے رسم و رواج، مذہبی تصورات، سیاسی، فکری اور سماجی رویوں کے تناظر میں مرتب کرتا ہے۔
تلمیح کی طرح ترکیب بھی محاورے کے ساتھ معنوی ربط بھی رکھتی ہے اور ظاہری اور لفظی اختلاف بھی۔ دراصل ترکیب ایک ایسی اصلاح ہے، جس میں دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو کسی حوالے سے باہم مربوط کیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض اوقات مضاف اور مضافِ الیہ کو حرفِ اضافت کی مدد سے جوڑ دیا ہے، بعض اوقات صفت اور موصوف کو حرفِ اضافت کے تناظر میں باہم جوڑ کر ایک ترکیب بنائی جاتی ہے۔ بیشتر پاکستانی زبانوں کی ترکیب سازی کے عمل میں فارسی کی تراکیب کے نظام کے اثرات بے پناہ ہیں، بلکہ برصغیر پاک و ہند میں بولی جانے والی مسلم اکثریت کی تمام زبانیں اپنی ترکیب سازی کے نظام کو فارسی سے مستعارلیتی رہی ہیں۔ نوے فیصد سے زیادہ تراکیب سازی فارسی قواعد کے زیر اثر ہوئی ہے، ہوتی رہی ہے۔ محاورہ اپنے خارجی پیکر میں ترکیب ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر محاورہ ایک ترکیب ہوتا ہے، لیکن ہر ترکیب محاورہ نہیں ہوتی۔ محاورے اور ترکیب کا کارجی آہنگ مختلف ہوتا ہے، لیکن ان کے معنوی نظام میں، معنوی یکجائی کے عناصر موجود ہوسکتے ہیں۔ مختصریہ کہ جب ہم ان تمام مذکورہ اصطلاحات (روزمر، ضرب المثل اور تلمیح) کے تناظر کو محاورے کے ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام اصطلاحات کے پس منظر میں موجود معنوی رویہ تو تقریباً یکساں رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کا خارجی آہنگ اور رنگ ڈھنگ مختلف ہوتا ہے۔
حوالہ جات
۱۔ غلام ربانی، الفاظ کا مزاج، لاہور، رابعہ بک ہاوس، س ن، ص ۹۰
۲۔ شان الحق حقی ( دیباچہ) جامع الامثال ( اُردو ضرب الامثال کا ایک جامع معجم)، مرتبہ: وارث
سرہندی، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۸۶ء ص: ح
۳۔ شان الحق حقی (دیباچہ) جامع الامثال، ص: و
۴۔ افتخار عارف (پیش لفظ) اُردو میں مستعمل عربی و فارسی ضرب الامثال، مصنفہ: مقبول الٰہی، اسلام
آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۶ء ص: ندارد
۵۔ سیفی، ڈاکٹر ہمارے محاورے، لاہور، رابعہ بک ہاوس، س ن، ص ص : ۸،۷
۶۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر اردو زبان اور لسانیات، لاہور، سنگِ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۷ء ص: ۶۳
۷۔ وحید الدین، مولوی، افاداتِ سلیم، لاہور، شیخ مبارک علی، اُردو بازار، ۱۹۷۲ء ص: ۱۰۴