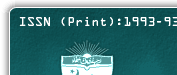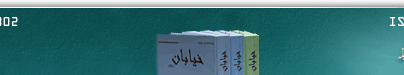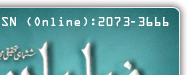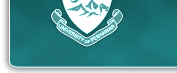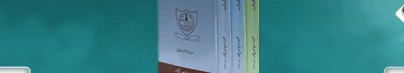قومیت کی تعمیر میں زبان کی اہمیت
(پاکستان۔ اردواور دوسری پاکستانی زبانون کے تناظر میں)Abstract
This article provides different aspects of research that play vital role in the importance of language and development of nation with special reference of Urdu. Pakistan is an outcome of two nation theory in subcontinent which emphasizes Muslim as different nation from Hindus due to so many religious, cultural and social factors. Urdu (Quranic Script) was also an important facto which separates the Muslim and Hindus. This article provides considerate material about the facts that Urdu played, great role not only in making Pakistan but its also binding factor in different parts of Pakistan. This article not only provides Ethnographic background to the issue but also discourse the role other Pakistani languages and their importance in development of future format of Urdu language of Pakistan.
قومیت جسے انگریزی لفظ Nationality کااردو متبادل کہہ سکتے ہیں۔ سیاسی اصطلاح ہونے کے ساتھ مختلف تہذیبی، ثقافتی، مذہبی، معاشرتی اور ادبی جہتوں اور سلسلوں پر ممشتمل ایک اہم جغرافیائی اور تمدنی اصطلاح ہے جو گزشتہ صدی سے کچھ زیادہ ہی زیر بحث چلی آرہی ہے خصوصاً پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا جس نئے نقشے سے متعارف ہوئی اس سے قومیت کی اصطلاح کے کئی نئے مفاہیم سامنے آئے عمرانیات اور سیاسیات سے تعلق رکھنے والے دانشوروں نےاپنے اپنے حوالے سے اس لفظ کی تفسیروتشریح کی یہ تشریح اپنےطور پر ایک جداگانہ مطالعے کی متقاضی ہے اس تشریحی مواد میں قومیت کی لغوی معنویت سے اس کے اصطلاحی مفاہیم تک ایک طویل سلسلہ بحث ملتا ہے۔ قومیت کی تشریح جغرافیہ کے حوالے سے بھی ہوئی اور سیاسی وتاریخی سیاق و سباق میں بھی اس پر روشنی ڈالی گئی ان تمام تشریحات میں جو عناصر مشترک ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ قومیت کا تعلق انسانی گروہ اور معاشرے سے ہے۔ انسانوں کے لیے ایسے ہجوم گروہ اور آبادی سے جو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۱۔ کسی جغرافیائی اکائی میں سکونت پزیرہو یہ جغرافیائی اکائی جدید سیاسی اصطلاح میں کوئی خطہ زمین، ریاست، صوبہ یا ملک ہوسکتا ہے۔
۲۔ جس کے رہنے والے اپنے سماجی رویوں اور مذہبی اقداروروایات اور تہذیبی وثقافتی رسومات میں مماثلت رکھتے ہوں۔
۳۔ ان کا تہذیبی وثقافتی اثاثہ اور علم ودانش کا سرمایہ مشترک صفات کا حامل ہو۔
۴۔ جن کے اندر ایک لسانی وحدت اور زبان وبیان کی یک رنگی موجود ہو۔
تعجب کی بات ہے کہ مذکورہ بالاجغرافیائی، سماجی، مذہبی، تہذیبی و ثقافتی اقداروروایات کی مماثلت کے باوجود یہ سب کچھ قومیت کی تعریف پر ہو بہو پورا نہیں اترتا اگر جغرافیہ کو قومیت کی بنیاد مانا جائے تو پھر وہ کُروہ کہاں جائیں گے جو ایران ترکی اور قبرص کئی ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کشمیری قوم بھارت اور پاکستان میں منقسم ہے زبان کو اس کی بنیاد جانا جائے تو ہم متعدد ملکوں عراق، سعودی عرب، کویت، شام، مصر، اردن وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ عربی زبان بولنے والے یہ ملک ایک قومی وحدت میں منسلک نہیں اگر مذہب کو قومیت کا لازمی جزقرار دیا جائے تو ملائیشیاء پاکستان ایران اور متعدد عرب ملک اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی ایک قومیت نہیں کہلاتے۔
جغرافیہ زبان اور مذہب کے اشتراک کےباوجود مختلف ملک مختلف قومیتوں کے حامل ہیں بعض صورتوں میں ہم ایک خطہ زمین، ریاست یا ملک کے اندر کلچر اور زبان کی بنیاد پر مختلف قومیتوں کے جداگانہ رنگ روپ دیکھتے ہیں یوگوسلاویہ اس کی تازہ مثال ہے جہاں صدیوں سے آباد لوگ اب بوسنیا، ہرزیگوینا، کوسووو اور دوسری جغرافیائی اکائیوں اور ریاستوں میں اپنا اپنا قوامی سفر از سرنوشروع کر رہی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر بھی اپنے جداگانہ وجود پر مطمئن ہے اگر زبان کسی مشترکہ قومیت کی ناگزیر بنیاد ہوتی تو مشرقی اور مغربی بنگال کب کے مل چکے ہوتے بنگلہ دیش میں مشترکہ لسانی خصوصیات کے سبب کبھی مغربی بنگال سے الحاق کرنے کا تصور تک نہیں کیا گیا۔ یورپ کے بہت سے ملک بھی جغرافیائی قربت اور لسانی یکسانیت کے باوجود الگ الگ ملکوں کے باشندے ہیں تہذیب وثقافت کا اشتراک بھی کلی طور پر انہیں ایک قوم نہیں بناتا حالانکہ انگلینڈ آئرلینڈ سکاٹ لینڈ اور اسی طرح سکینڈے نیوین ممالک ناروے، ڈنمارک اور سویڈن وغیرہ کئی مشترک تہذیبی مماثلیں رکھتے ہیں۔ معروف فرانسیسی ماہر لسانیات مؤرخ اور ناقد ارنسٹ ریناں (Ernest Re-Nan) نے اپنی معروف کتاب "قوم کیا ہے"؟ (Quest-ee-Qu’ane Nation) مطبوعہ پیرس 1882میں قوم اور قومیت کے مسائل پر مختلف پہلوؤں سے بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
"فرانسیسی قوم کلٹنی، آئی بیریائی، اور ٹیوٹنی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ جرمن قوم ٹیوٹنی، کلٹنی اور اسلانی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نوع کا نسلی مرکب ہریورپی ملک میں پایا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ایک مشترکہ زبان ایک قوم کی تشکیل کرتی ہے؟ ریناں کے بقول کہ "زبان لوگوں کو متحدہ تو کرتی ہے مگر انہیں ایک عام قومیت تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ برطانیہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ یا سپین اور لاطینی امریکہ میں ایک مشترک زبان قومیت کے اصول کو قائم نہ کرسکی۔ جبکہ سویٹزرلینڈ میں جہاں تین زبانیں بولی جاتی ہیں خود کو ایک قوم میں ڈھال لیا۔ ۔۔۔۔۔۔ (1)
سو۔۔۔۔۔۔ ثابت ہوا کہ بہت سی ایسی یک رنگیوں کے باوجود جو مذہبی، تہذیبی، لسانی اور ثقافتی رویوں سے متعلق ہیں قومیت کے بنیادی عناصر واضح نہیں یہ بھی ایک بدیہی امر ہے کہ قومیت کا مفہوم انہیں مماثلتوں اور مشترک اقداروروایات سے مل کر ترتیب پاتا ہے جو جغرافیہ، نسل، تہذیب، ثقافت، مذہب اور زبان کے مظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔
برصغیرپاک و ہند کے مسلمان قومیت کے ایک عظیم، منفرد اور تاریخ ساز تجربے سے گزرے بیسویں صدی کے آغاز میں پیدا ہونے والی سیاسی تحریکوں اور ان کے ردعمل سے پیدا ہونے والے حالات و واقعات نے یہاں دو قومی نظریہ کو جنم دیا اگرچہ اس نظریے کی ارتقائی شکلیں تحریک قیام پاکستان سے بہت پہلے سے نظر آنا شروع ہوجاتی ہے مگر علامہ اقبال کے تصورات اور قائداعظم محمد علی جناح کی فراست نے اس نظریے کے خدوخال واضح اور مربوط کئے اور یوں برصغیر پاک و ہند میں مذہب، تہذیب و ثقافت، رہن سہن اور کلچر کے فرق کے سبب ایک ہی خطہ زمین میں رہنے والے لوگ دو مختلف قومیں قرار پائے اس بارے میں قائداعظم محمد علی جناح کا یہ جملہ تاریخ ساز حقیقت کا مظہر ہے کہ "پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب یہاں ہندو نے پہلی بار اسلام قبول کیا تھا۔"
اس جملے کی معنویت شاید نئی نسل پر پوری طرح منکشف نہ ہو لیکن اگر تاریخ کے باطن میں اتر کر کئی صدیوں پہلے کی فضا میں جھانکا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہندو اپنی برادری سے علیحدہ رہنے پر مجبور کردیا گیا تھا اس کے ساتھ تہذیبی وثقافتی مقاطع کے سبب اس کو اپنے ساتھ بٹھانے، اپنے پیالہ میں پانی پینے سے منع کردیاگیاتھا۔ لہذٰا وہ ایک خطہ زمین، ایک نسل خاندان اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر میں رہنے اور ایک زبان بولنے کے باوجود دوسروں سے مختلف ہوگیا رہن سہن کے بعض یکساں طریقوں کے باوجود اپنی مذہبی اقدار کے سبب ایک مختلف قوم کا فرد بن گیا اس کی یہی بدلی ہوئی ذہنی کیفیت جو قبولیت اسلام کے بعد پیدا ہوئی اسے پرانے ہم قوموں سے ایک جدا قوم گردانتی ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد ہندوستانی مسلمانوں کا یہی اختلاف اور امتیاز ہے علامہ اقبال نے وطنیت اور قومیت کے اس فرق کو اپنی ایک نظم بعنوان وطنیت (یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے) میں واضح کیا ہے۔ اقبال وطن کے سیاسی تصور کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے
غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے
بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے
اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے (2)
اس نظم کے تناظر میں علامہ اقبال کا تصور وطنین اور قومیت نمایاں ہے دونوں کا گہرا اور بنیادی تعلق رنگ نسل جغرافیہ اور زبان کی بجائے دین سے ہے اقبال نے وطن اور قوم دونوں کو ملت کے نکتہ نظر سے دیکھا ہے۔
برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی جداگانہ شناخت کے لیے وطنیت کے اس نئے تصور کے ساتھ ساتھ اردو کی تاریخی حیثیت بھی پیش نظر رہنی چاہیے اس کے لیے درج ذیل دو اقتباسات دیکھیے جو قریب قریب نصف صدی کے فرق کے ساتھ ایک ہی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا اقتباس حافظ محمود شیرانی کی تحریر کا ہے جب کہ دوسرا پروفیسر مرزا محمد منور کا ہے۔
پروفیسر حافظ محمود شیرانی اردو زبان وادب کی جڑیں تلاش کرتے ہوئے لکھتے ہیں
"ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ زبان ہندوستان میں مسلمانوں کے داخلے اور توطن گزینی کا نتیجہ ہے اور جوں جوں اس کی سلطنت اس ملک میں وسعت اختیار کرتی گئی یہ زبان بھی مختلف صدیوں میں پھیلتی گئی دسویں صدی سے اس میں تصنیفات کا سلسلہ جاری ہوجاتا ہے جو سب سے پہلے گجرات میں اور بعد میں دکن میں شروع ہوتا ہے اس سے پیشتر اس زبان کے وجود کا پتہ صرف فارسی تصنیفات سے لگ سکتا ہے جو نویں آٹھویں اور ساتویں قرن ہجری میں ہندوستان میں لکھی گئی ہیں۔" (3)
اور بقول پروفیسر مرزا محمد منور:
"ہندوؤں کی اردو زبان میں زبان اشتراک کی حیثیت بھی اس لیے گوارا نہ تھی کی اس کا ظاہری پیکر بہرحال فارسی عربی تھا اور وہ مہاتماجی کے بقول قرآن کے حروف اور اسلوب کا مالک تھا اصلی تکلیف یہ تھی کہ اردو ابجد کی شکل عربی قرآن سے ملتی جلتی تھی اور قرآن کے آثار باقی اور جاری رہنا گویا مسلمان کو باقی رکھنے کی گنجائش پیدا کرنا تھا اور یہ کیوں کر ممکن تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"(4)
وہ آگے چل کر ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جس سے اردو زبان کے بارے میں ہندوانہ تعصب اور نمایاں ہوجاتا ہے۔
"مسلم لیگ کے چوتھے اجلاس میں یہ فریاد مسلمان نمائندوں نے پیش کی کہ کمیٹی کے ناظم تعلیمات نے مراسلہ جاری فرمایا ہے کہ پبلک کے سکولوں میں سے اردو کو الگ کردیاجائے اگر مسلمان اردو کی تعلیم جاری رکھنا چاہیں تو دینی تعلیم کی طرح اس کا اہتمام اپنے گھروں پر کریں اس طرح گویا اعلان کردیا گیا کہ ہندوؤں کا جس طرح اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح اردو سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ 37ء میں تشکیل پانے والی کانگریسی وزارتوں نے رہی سہی کسر پوری کردی رام راج قائم کرنے کی نیت سے نیک شگون کے طور پر تمام ہندوصوبوں کے وزراء اعلیٰ برہمن مقرر کئے گئے اب حال یہ ہوگیا کہ ڈاک خانہ والوں نے اردو میں تحریر کردہ منی آرڈر بھی قبول کرنے سے انکار کرنا شروع کردیا۔" (5)
مزرا صاحب اپنے مضمون "اردو اور تحریک پاکستان" میں اس مسئلے اور تنازع کا خلاصہ اس تاریخ ساز فقرے میں نکالتے ہیں کہ تحریک پاکستان کا محرک اول اگر اسلام تھا تو محرک دوم اردو زبان تھی"۔ یہ جملہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کی گواہی اردو زبان اور رسم الخط کے حوالے سے ہندوانہ ذہنیت اور تعصب کی کم و بیش ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے۔
اردو زبان سے ہندوؤں کے الگ ہونے اور اسے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص کردینے کا ایک تاریخی پس منظر ہے اس کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنے کی ضرورت ہے بریس پال (Bress Pail) کے بقول:
The Hindi Urdu controversy in the Punjab arose for the first time in 1882, a year after the decision to substitute Hindi in the Devanagry script for Urdu in Persian script in Bihar. The demand in the Punjab by the Urban, was the same and it was seen by both sides as an aspect of the Hindu-Muslim communal conflict.(6)
انجمن اسلامیہ لاہور نےاس تحریک پر احتجاج بھی کیا لالہ پت رائے معروف آریہ سماج لیڈر اگرچہ ہندی حروف تہجی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے ہندی قومیت کے زیر اثر اس تنازعہ میں شامل ہوگئے انہیں یقین تھا کہ ہندی زبان ہندی قومیت کی بنیاد بن سکتی ہے ان کے خیال میں ہندونینشل ازم کی سیاسی یک جہتی کے لیے ہندی اور دیونا گری کافروغ ضروری ہے۔
اس لسانی تنازعہ کو ہندوستان کی سیاست نے مزید ہوادی اس کی تفصیلات کے دستاویزاتی شواہد موجود ہیں جو بابائے اردو عبدالحق اور گاندھی جی سے مکالمہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ جس کی نشاندہی "اردو دستاویزات" مطبوعہ مقتدرہ قومی زبان میں وضاحت سے موجود ہے۔ یوں رفتہ رفتہ اردو (قرآنی رسم الخط میں) مسلمانوں کے ساتھ ہی منسوب ہوگئی یا یوں کہیے کہ اسے مسلمانوں کے ساتھ خاص کردیا گیا۔
ان سیاسی حالات میں مسلمانوں کے ادب اور تہذیب وثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے اردو زبان اور اسکے رسم الخط کے تحفظ کا مسئلہ پیدا ہوا یہی وجہ ہے کہ مسلمان رہنماؤں نے اپنی تحریروں، تقریروں اور اخبارات میں اس اہم مسئلہ کی طرف توجہ کی اور اردوزبان اور رسم الخط کے تحفظ کے مسئلہ کو اپنی قومی بقا اور شناخت کے ساتھ جوڑ دیا ار یہ ایک حقیقت بھی تھی کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلامی مذہب و عقائد، روایات و آثار، شعروادب اور تہذیب و ثقافت سے وابستہ آثار کا بہت بڑا سرمایہ اردو ہی کی صورت میں موجود تھا یہ سرمایہ اپنے مخصوص رسم الخط سے بامعنی تھا دیونا گری رسم الخط میں اردو کی ہرشکل پر ہندی کا گمان گزرتا ہے لہذٰا مسلمانان ہند نے نجی دائروں سے سرکاری سطح تک ہر جگہ اردو زبان کو اپنی قومیت سے جوڑے رکھا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کی جانے والی قراردادوں میں ایک وقیع حصہ ایسی قراردادوں پر مشتمل ہے جو اردو زبان اور رسم الخط کے تحفظ کے بارے میں ہیں۔
کسی قوم کے خدوخال اس کے ادب میں نمایاں ہوتے ہیں قوموں کی تاریخ کا آئینہ وہ آثار، کتابیں، دستاویزات، اخبار و رسائل اور شعروادب پر مشتمل وہ تحریریں ہوتی ہیں جو اس قوم کے اہل قلم لکھتے ہیں۔ سال بہ سال اور عہد بہ عہد اس قوم کی اجتماعی سوچ اور دانائی اس کے ادب کے اندر بولتی ہے قدیم یونانی تہذیب ہو یا ہندی تہذیب ان زبانوں کے ادب کے اندر ان قوموں کا تمدن، تہذیب، معاشرت، سماج کے ادب آداب، رہن سہن، لباس، خوراک، مذہبی اقداروروایات، اہم تاریخی شخصیتیں، ان کے دیوی دیوتاؤں کے حوالے، خدا کا تصور اور ان کی اجتماعی خوشیوں اور دکھوں سےلے کر اجتماعی امنگوں اور قومی مقاصد تک کی جھلکیاں ان کی تحریروں میں ملتی ہیں یونانی زبان میں ہومر سے منسوب نظمیں اوڈیسی اورایلیڈ اور ہندی زبان میں مہابھارت اور رامائن جیسے عظیم ادب پاروں میں یونانی اور ہندی تہذیب ومعاشرت کے قدیم نقوش اس وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں کہ اگر یونان و ہند کے تاریخی آثارہمارے سامنے نہ بھی ہوں تو ان ادب پاروں کے تجزیاتی مطالعے سے ان ملکوں اور تہذیب کی پرانی معاشرت، آلات جنگ، ملبوسات، زیورات، مذہبی عقائد، تمدنی احوال، عقائدورسومات، انسانی رشتے، محبتیں، لڑائیاں، اچھائی اور برائی کے معیارات، عبادات کے طریقے اور سینکڑوں دوسرے عمرانی اور سماجی رویوں کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔
قومیت کی تعمیر میں ادب کا خاص کردار ہوتا ہے ادب کسی بھی زبان، تہذیب ملک اور زمانے کے بہترین افکار کا تحریری منظرنامہ ہوتا ہےاور اس زبان، تہذیب ملک اور زمانہ کا پورا ماحول اس کے اندر بولتا ہے۔ اردو اس اعتبار سے بہت ثروت مند ہے کہ اس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے عناصر شعور امنگیں اور احوال ایک ادبی قرینے (Literal Organization) اور تخلیقی شائستگی اور شکوہ (Eative Decorum) کے ساتھ ملتے ہیں۔ اردو ادب اپنے تاریخی اور ارتقائی سفر میں برصغیر پاک و ہند میں رہنے والی سبھی چھوٹی بڑی قومیتوں کے اجتماعی احوال و افکار کا مظہر ہے۔ اس کی تخلیق اور فروغ میں اس جغرافیے میں بسنے والے تمام اہل قلم، ادیبوں، شاعروں اور تخلیق کاروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے امیر خسرو سے لے کر عہد حاضر تک مسلمان اور ہندو ادیبوں کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے اردو ادب کی آبیاری کی ہندومسلم تہذیب و معاشرت کے عناصر اور مذہبی عقائدورسومات کی بھرپور عکاسی اردووشعر و ادب میں موجود ہے امیر خسرو سے منسوب قدیم شعری نمونوں دوہوں اور دوسرے نظم پاروں سے لے کر نظیر اکبر آبادی تک میں اس مخلوط معاشرت کی جھلکیاں بہ آسانی دیکھی جاسکتی ہیں جو برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی رشتوں اور تعلقات کی مظہر ہیں یہ سلسلہ انیسویں صدی کے آخر تک نمایاں طور پر نظر آتا ہے لیکن بیسویں صدی کے آغاز میں سیاسی بیداری کے سبب اردو ادب میں قومی اور ملی شعور کا ایک اور دھارا زیادہ نمایاں ہوا جو پہلے دو قومی نظریہ اور بعد میں پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا۔
قومی اور ملی شعور کا یہ تشخص اپنی ایک مخصوص تاریخی پس منظر رکھتا ہے بہت سے اہل قلم نے ۱۸۵۹ء کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں بڑھتے ہوئے اختلافات کے پیش نظریہ محسوس کرنا شروع کردیا تھا کہ سیاسی بیداری اور عام ہوتے ہوئے شعور کے نتیجہ میں دونوں قوموں کا اکٹھا رہنا مشکل ہے۔ مولانا حالی نے حیات جاوید میں سرسید کے حوالے سے بھی ان خدشات کا اظہار کیا ہے ان کے خیال میں سرسید احمد نے 1867 میں ہی اردو ہندی تنازعہ کے پیش نظر مسلمانوں اور ہندوؤں کے علیحدہ ہوجانے کی پیش گوئی کر دی تھی۔ انہوں نے اس کا ذکر ایک برطانوی افسر سے کیا تھا کہ دونوں قوموں میں لسانی خلیج وسیع ترہوتی جارہی ہے۔ اور ایک متحدہ قومیت کے طور پر ان کے مل کے رہنے کے امکانات معدوم ہوتے جارہے ہیں۔ اور آگے چل کر مسلمانوں ار ہندوؤں کی راہیں جدا ہوجائیں گی۔ (7)
اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کا یہ اقتباس بھی ملاحظہ کریں۔ جس میں مسلمانوں کے جداگانہ ملی تشخص کے ساتھ ساتھ ہندوانہ تعصب کی بات بھی کی گئی ہے۔
موجودہ حالات میں تقسیم ہند ہی مسئلہ کا واحد حل ہے کیونکہ ہم مسلمان اپنی جداگانہ ثقافت، تہذیب، زبان، ادب، آرٹ اور فن تعمیر، قوانین اور اخلاقی ضابطوں، رسوم، کیلنڈر، تاریخ اور روایات اور ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہیں ہندوستان کبھی بھی ایک کامل نہیں رہا جس گائے کو میں کھانا چاہتا ہوں ہندو اسے ذبح کرنے سے منع کرتے ہیں حدیہ ہے کہ جب بھی کوئی ہندو مجھ سے ہاتھ ملاتا ہے تو اسے بعد ازاں اپنا ہاتھ صاف کرنا پڑتا ہے۔ (8)
علامہ اقبال کے افکار خصوصاً الہ آباد (1930) نے اس تصور کو زیادہ نمایاں کیا اور اسے ایک ٹھوس تاریخی اور سیاسی نظریہ کی صورت دی مسلم پریس، ادیبوں اور دانشوروں کی تحریروں، سیاسی رہنماؤں کی تقریروں اور مسلمانان ہند کے اجتماعی شعور نے اس نظریہ کی آبیاری کی اور یوں اردو ادب کا تخلیقی دھارا قیام پاکستان سے پہلے ہی ہندوستانی مسلمانوں کے افکاروعقائد اور تہذیب و معاشرت کی ترجمانی کا فریضہ سرانجام دینے لگا (9)
یوں پاکستان کے قیام سے قبل کے شعروادب کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی چھاپ واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی۔ ہندوؤں کے سیاسی قائدین کا تعصب آزادی ہند کے بعد بھی جاری رہا سیکولرازم کے دعوؤں کے باوجود وہاں اقلیتیں ہمیشہ ریاستی ہندوانہ جبراور تشدد کاشکار ہیں۔ ہندوستان میں اب تک ایسے ہزاروں مسلم کش فسادات ہوچکے ہیں جن میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کی املاک لوٹی گئیں عورتوں کی آبروریزی کی گئی اور انہیں قتل کیا گیا۔ کہنے کو انڈیا سیکولر سٹیٹ ہے مگر یہ سیکولرازم بھی برائے نام ہے۔ بھارتی صحافت وسیاست میں سیکولرازم کی بات تو ہوتی ہے مگر حیرت کی بات ہے کہ 1976 تک یہ لفظ بھارتی آئین کا حصہ نہ بن سکا۔ سیکولرکا لفظ دسمبر 1976 میں ایک ترمیم کے ذریعے بھارتی آئین کے دیباچے میں رسما شامل کردیا گیا مگر اس کی ضروری تفصیل و تعریف سے گریز کیا گیا۔ یہ ترمیم ملاحظہ ہو۔
The Declaration by the 42nd Amendment inserting the word Secular in the preamble amounts to this effect ‘we the people of India Constitute India into a Socialist Secular State as we declare so on 18th December 1976’. (10)
قیام پاکستان کےبعد اردو ادب میں ملی رجحانات کے خدوخال زیادہ نمایاں ہونے لگے اور اردو ادب میں نمایاں طور پر ایک ایسے تخلیقی رجحان کا آغاز ہوا جسے پاکستانیت سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ پاکستانیت کے عناصر اردوکے علاوہ پاکستان کی دوسری زبانوں کے ذریعے بھی فروغ پذیر ہوئے۔ اور مسلسل پروان چڑھ رہے ہیں۔ سندھی ادب سیمینار جام شورو (منعقدہ ۱۹۸۴ء) میں سندھ کے عظیم محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ اپنے صدارتی خطبے میں پاکستانی ادب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
"پاکستانی ادب کیا ہے پاکستانی ادب اردو اور ملک کی دوسری زبانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے ادب کے دائرے میں پاکستان کی سب زبانیں ہماری اپنی زبانیں ہیں اس لیے فقط اردو ادب کو قومی کہنا عقلمندی کی بات نہیں کیونکہ اسی سبب سے یہ اثر پختہ ہوجائے گا کہ ملک کی دوسری زبانوں کے ادب کو قومی ادب نہیں سمجھا جاتا اس سوچ کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اردو ملک کی دوسری زبانوں سے نفسیاتی طور پر الگ ہوتی رہے گی۔
پاکستانی ادب ملک کی جملہ زبانوں کا مشترک خزانہ ہے اگر ہم خلوص دل سے وطن دوست بن کر لسانی برادری اور رواداری کے اس نظریہ پر عمل کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ملک کی جملہ زبانوں کے ادب کو پاکستانی ادب کے دائرے میں ایک قابل فخر مقام حاصل ہوگا۔" (11)
بلاشبہ پاکستانی ادب پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کے ادب پر مشتمل ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس میں سب سے نمایاں، وسیع اور منفرد اظہار اردو زبان ہی کے وسیلے سے ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو دوسری زبانوں کی نسبت اپنا لسانی اور تخلیقی دائرہ زیادہ وسیع رکھتی ہے اس میں تحریری ادب زیادہ ہے کتب و اخبارات اور رسائل وجرائد میں اردو زبان وادب کا مواد زیادہ دستیاب ہے نیز جامعات میں تدریس اور تنقیدی و تحقیقی حوالوں سے اردو کاکام بحیثیت مجموعی دوسری زبانوں سے زیادہ حجم (Volume) کا حامل ہے۔ گزشتہ آٹھ سالوں میں لکھے جانے والے ادب کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اہل قلم کے ذاتی مشاہدات و تجربات اور محسوسات و خیالات کے ساتھ ساتھ اجتماعی مسائل و احوال کے بیان میں اردو کی خدمات قابل قدر ہیں اردو ادب ملی امنگوں کا ترجمان بھی رہا ہے اور اس کے ذریعے قومی تشکیل National Constructionکی بھی کئی صورتیں پیدا ہوئی ہیں۔
یہاں ایک اور مسئلے کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ پاکستان میں بولی جانے والی اردو کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دکن، دلی اور لکھنؤ سے ہوتے ہوئے اردو کے لسانی رویے اور خدوخال وقت کے اثرات اور تبدیلیوں سے دو چار ہوتے رہے۔ پاکستان میں بولی جانے والی اردو کی صورت اب اردوئے معلیٰ کی نہیں۔ بلکہ عام بول چال اور اخبارات ورسائل میں نظر آنے والی زبان کی ہے۔ ویسے بھی زبان کے کئی درجے اور معیارات ہوتے ہیں۔ بقول شان الحق حقی:
"۔۔۔۔۔۔۔ ایک جمے جمائے معاشرے میں ہر زبان کی ایک معیاری بولی ہوتی ہے اور کئی فروعی یا تحتی بولیاں جو اس کے اردگردرستی بستی ہوں ایک انگریز مصنف Erntwistle نے اس کا نقشہ یوں پیش کیا ہے کہ زبانوں کی ایک کھڑی تقسیم ہوئی ہے اور ایک پڑی تقسیم ۔۔۔ ڈایلیکٹ افقی یا پڑی تقسیم میں آتے ہیں ان کا اختلاف جغرافیائی یا مقامی ہوتا ہے کھڑی یا عمودی تقسیم طبقہ داری ہوتی ہے۔"
ایک اور مصنف Eric Partrige نے اپنی کتاب Slang and Standard English میں انگریزی زبان کی حسب ذیل تحتی بولیاں گنوائی ہیں۔
Standarad … ents … -Slang … -Colloqinal … -Vulgarism
اور اسٹینڈرڈ انگلش کے تین مدارج قرار دئیے ہیں۔
Familiar English – Ordinary English – Literary English
میں اس تقسیم سے متفق نہیں ادبی زبان کو اس طرح عام بول چال اور روزمرہ سے الگ کرنا ایک بے تکی اور فرسودہ سی بات ہے لیکن دراصل معیار کا پورا مسئلہ ہی نئے سرے سے نمودوفکر کا محتاج ہے۔(12)
پاکستانی قوم کے اجتماعی شعور اور اس کے تہذیبی ثمرات (دانش و فرہنگ، ادبیات و شعریات اردو زبان کے مختلف اسالیب وانداز وغیرہ) اسی صورت میں حاصل ہوسکتے ہیں جب آبادی کے وسیع ترطبقے کے لسانی وثقافتی تجربات اور معمولات کو اردو زبان کا رسمی حصہ ہی نہ بنایا جائے بلکہ اسے ایک قابل قبول فرہنگ مشترک کے معیار تک لایا جائے۔ "فرہنگ مشترک" کے عنوان سے ڈاکٹر پرویز ناتل خانلری اپنے مضمون کا آغاز ہی ایک ایسے مسئلے سے کرتے ہیں۔
"یکی ازاموری کہ درآن کثرت شریکان مطلوب بہ مایہ رونق و اعتبار است فرہنگ ملی است۔ فرہنگ ہر قوم محصول اندیشہ بہ ذوق بہ تجربہ ہائی عمود افراد آن درگزشتہ وحال می باشد۔ ازایں جاست کہ ہر چہ قلمرو فرہنگی وسیع ترباشد گروہی بزرگ تردرایجاد و تکمیل آں می کو شند واز کوششِ ایشاں نتیجہ ای عظیم تروکامل تر حاصل میشود ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ایں زبان البتہ دراصل بہ یکی ازنواحی آن سرزمینِ اختصاص داشتہ است اما پس ازآنکہ ایں طریق توسعہ و کمال یافت دیگر بہ ناحیہ خاصی تعلق ندارد بلکہ زبان مشترک ہمہ مردماں آن سرزمین محسوب میشود" (13)
پاکستان میں فرہنگ مشترک کے عظیم اور کامل تر ثمرات حاصل کرنے کے لیے اس خطہ زمین میں رہنے والے تمام علاقائی گروہوں کی اجتماعی دانش اور ان کی زبانوں اور لوک دانائی کو ایک قرینے اور شائستگی سے اردو زبان کا حصہ بنانا ہوگا۔
پاکستان میں اردو کے معیار کے ساتھ ساتھ علاقائی کے تنوع اور ان کے اثرات سے انکار مشکل ہے اردو مقامی زبانوں کی ہم رشتہ ہے ان میں معنوی اور قواعدی مماثلتیں اور بڑا اشتراک ہے اردو لغت، جسے اردو ڈکشنری بورڈ کراچی کے زیر اثر مرتب کیا جارہا ہے اور جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اردو کے ایک معیار کو سامنے لاتی ہے اس لغت میں الفاظ کو ان کے اصل اور اشتقاق کے ساتھ ساتھ مختلف تاریخی ادوار کی مثالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔
موجودہ اردو میں ہر دور اور علاقے کے لسانی اثرات موجود ہیں ان کی موجودگی زمانے کے ساتھ ساتھ ایک فطری انداز کی حامل ہے انہیں زبردستی اردو کا حصہ نہیں بنایا گیا دکن، پنجاب، سندھ کھڑی بولی اردو دوسری زبانوں کی آمیزش نے اسے ایک ایسی لسانی جامعیت اور ہمی گیریت عطا کی ہے جو برصغیر پاک و ہند میں اردو کے علاوہ کسی زبان کا مقدر نہیں ہوئی خصوصاً ۱۹۴۷ء کے بعد اردو نے پاکستان کی دوسری لسانیوں تبدیلیوں کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس قبولیت کے لیے آیندہ کے در بھی وار رکھے۔ پاکستان کی قومیت میں اردو ایک لسانی قدر ہی نہیں بنیادی جزو کا درجہ بھی رکھتی ہے یہ ہمارے جغرافیے کے ساتھ ہماری موجود تاریخ کی توانا شناخت ہے اور جدید الفاظ کو قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ نئے تہذیبی، صحافتی، سماجی ثقافتی اور سائنسی اثرات سے بھی برابر استفادہ کر رہی ہے پاکستان کے ثقافتی اجزاء اور مختلف تہذیبی اکائیوں اور لسانی وحدتوں سے جڑے ہوئے لوگوں کے درمیان پھیلے ابلاغی فاصلوں کو اردو ہی نے جوڑ رکھا ہے۔
بلاشبہ اردو دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی بولی اور سمجھی جارہی ہے مگر پاکستان میں اردو کے استعمال کی شان اور اثر ہی اور ہے ایک ایسی شان جس سے ہماری قومیت تابناک ہے اور ایک ایسا خوشگوار اثر جس نے ہماری پوری آبادی کو اپنی برکت کی فضا میں سنبھال رکھا ہے خنجراب کی چوٹیوں پر جہاں شنا اور بروشسکی بولی جاتی ہے دونوں آبادیوں اور علاقوں کے لوگ آپس میں گفتگو کے لیے اردو ہی استعمال کرتے ہیں۔
اردو کو پاکستان میں جو بین الطبقاتی زبان Inter Zonal Link Language کی حیثیت حاصل ہے وہ اور کسی زبانوں کو نہیں اردو ہمارے نزدیک اب ایک زبان ہی نہیں پاکستان کی ایک توانا شناخت اور مکمل پہچان کا درجہ رکھتی ہے اب اپنے امکانات کے لیے ہماری قومی زندگی ہی اردو کا دامن نہیں پکڑے ہوئے ہمارے ایمان وعقائد کی تفاصیل بھی تبلیغ وترسیل کے لیے اردو کے لب و لہجہ سے جڑی ہوئی ہیں بلاشبہ پاکستان میں اردو کا ظہور ایک ایسی لسانی وحدت اور یک جہتی کی علامت کے طور پر ہوا ہے جس نے ہمیں ایک منظم ثقافت اور قومیت کا شعور عطا کیا ہے۔
پاکستان میں زبان اردو کا مسئلہ اس کی تخلیق سے قبل ہی سے اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا مگر قیام پاکستان کے بعد ایک رابطے کی زبان Langua Franca کے طور پر اس نے سماجی و معاشرتی اظہار کے لیے ایک دوسرے کو آپس میں اس طرح جوڑا ہوا ہے کہ اب اس کا وجود استحکام پاکستان کا ناگزیر حوالہ بن گیا ہے۔
پاکستان کے لیے اردو کی اہمیت کیا ہے؟ یہ نکتہ سنجیدہ اہل فکر کی طبقے کی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں رہا۔ "تعلیمی مقالات" کے مرتبین نے پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے اردو زبان کو نہ صرف ناگزیر قرار دیا ہے بلکہ اس کی طرف مسلسل توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ان کے بقول:
"اہل پاکستان کو اردو کی جامعیت کے ساتھ ساتھ یہ ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ ملکی اتحاد میں زبان کا کیا مقام ہے اور قومیت Nationality کے ارتقاء اور قوم Nation کی تعریف میں زبان کیا کام انجام دیتی ہے۔(14)
یہ ایک حقیقت ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اردو، سیاسی، فکری، تاریخی تناظر میں فطری طور پر پاکستان کے ساتھ مربوط ہوگئی اب یہ پاکستان کے موجودہ دستور (اور سابقہ دستوروں کے حوالے سے بھی) پاکستان کی قومی زبان ہے اور گزشتہ چھ دہائیوں سے اس میں شعروادب، تاریخ وتنقید، تحقیق و علوم کے ساتھ ساتھ صحافت اور ابلاغیات کے رشتے اتنے گہرے ہوچکے ہیں کہ اس خطے میں بسنے والوں کی تخلیق اور فکری کارکردگی کا غالب ظہور اردو ہی کے حوالے سے ہورہا ہے یہی ہمارے بیان وترسیل کا ذریعہ ہے اور یہی ہماری قومی شناخت کا اہم نشان پہچان اور اعتبار اگرچہ اردو زبان وادب کے مراکز ہندوستان اور دوسری دنیا میں موجود ہیں لیکن اس کی پہچان کا غالب حوالہ اب پاکستان ہی سے وابستہ ہے۔
پاکستان کی دوسری علاقائی زبانیں جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے اپنے ثقافتی وتہذیبی میل جول سے اردو کی آبیاری کر رہی ہیں اور اس کے لغوی اثاثے اور اسلوبیاتی ورثے کو اپنے تہذیبی وثقافتی ماحول اور لسانی وسماجی فضا (Ethnographic Atmosphere) میں غیر محسوس طور پر بڑھاوا دے رہی ہیں ۔۔۔۔ اردو بھی پنجابی، بلوچی، سندھی ،پشتو اور دوسری پاکستانی زبانوں سے الفاظ، لہجے اوراسالیب کشید کر رہی ہے اور مختلف قومی اداروں اور جامعات میں اردو سے ان زبانوں کے لسانی روابط اور اشتراک پر تنقیدی و تحقیقی کام ہو رہا ہے سیاسی نعرہ بازی اور گروہی تعصبات سے قطع نظر فطری انداز میں اردو کا ان زبانوں سے لین دین کا عمل جاری ہے مستقبل کی اردو میں یہ عمل اور نمایاں اور تیزتر ہوگا اور قومیت کا یہ نشان اور پہچان۔۔۔۔۔۔۔۔ اردو اسی خطہ زمین پر انہی زبانوں کے جلو میں پھولے پھلے گی اور مزید ثروت مند ہوگی۔
ہور |
زباناں |
کندھاں |
وانگوں |
اردو |
چھت |
دے |
وانگ |
کندھاں |
جنیاں |
اُچیاں |
ہوون |
چھت |
دا |
مان |
ودھان |
'اردو' کے عنوان سے لکھی گئی اس مختصر سی پنجابی نظم کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ (پاکستان میں بولی جانے والی) اور زبانیں دیواروں کی طرح ہیں اردو چھت کی مانند ہے جیسے جیسے دیواریں سربلند ہوں گی گھر کی چھت کا مان بھی بڑھائیں گی۔
حوالہ جات
۱۔ عزیز احمد، پروفیسر: برصغیر میں اسلامی جدیدیت (ترجمہ ڈاکٹر جمیل جالبی) ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور 1989 ص ۲۳۴
۲۔ علامہ اقبال: کلیات اردو اقبال اکیڈمی لاہور ۱۹۹۵ء ص ۱۸۷
۳۔ حافظ محمود شیرانی: مقالات (جلد اول) مرتبہ مظہر محمود شیرانی مجلس ترقی ادب لاہور 1966ص۷
۴۔ مرزامحمدمنور، پروفیسر: اردو اور تحریک پاکستان مضمون مشمولہ اردو کانفرنس خانیوال ۱۹۸۷ ضلعی و دفتری زبان خانیوال ص ۳۸۔
۵۔ ایضاً ص ۴۰
۶۔ Bress Paul R. Language, Religion and Politics
Cambridge University Press 1974 p87
۷۔ حالی الطاف حسین مولانا: حیات جاوید کانپور ۱۹۰۱ء ص ۲۶۷
۸۔ خورشید ڈاکٹر عبدالسلام: ڈاکٹر روشن آراراؤ، تاریخ تحریک پاکستان مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد ص۲۷۸
۹۔ قتیل شفائی: کلیات قتیل شفائی لاہور
۱۰۔ بھارتیہ وی پی: (Religion-State Relationship & Constitutional Rights p & a deep publication 1987 p 44) India New Delhi
۱۱۔ شوق، ڈاکٹر نوازش علی: قومی زبان اور علاقائی زبانیں مضمون شمولہ اردو کانفرنس ۱۹۸۷ء خانیوال، خانیوال ضلعی مجلس زبان دفتری ۱۹۸۹ء ص ۴۸
۱۲۔ حقی شان الحق پروفیسر: نقدونگارش مکتبہ اسلوب کراچی ۱۹۸۵ء ص ۱۳۰
۱۳۔ پرویز ناتل خانلری ڈاکٹر: ہفتادسخن (جلد اول) انتشارات طوس تہران ۱۳۷۷ (ش) ص ۳۶۱
۱۴۔ تعلیمی مقالات: مجلس تعلیمات پاکستان لاہور ۱۹۶۷ء ص ۳۱
۱۵۔ ریاض مجید: توے دے تارے مسلم پنجابی مجلس فیصل آباد ۱۹۸۷ ص ۷۳