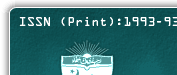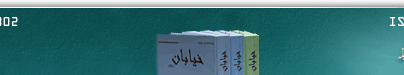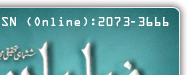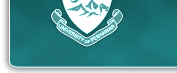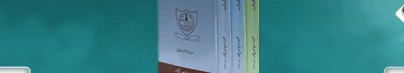تہذیب و ثقافت کا لسانی مطالعہ
Abstract
This paper is on the relation of language and culture. This is known fact that language is a part and partial of culture and divination. In this paper the writer has discussed the strong ling and basic roots between language and couture and also analyzed the difference of culture and civilization in a scientific way and proper research methodology.پاکستان کا موجودہ جغرافیہ 1947ء سے پہلے ہندوستان میں شامل تھا جس میں اب چار بڑی تہذیبی آ بادیاں موجود ہیں۔ سندھیِ، پنجابی، پشتون اور بلوچ۔موجودہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ ہزاروں سال قدیم ہے لیکن تاریخ میں یہ ہندوستانی ورثے کی حیثیت سے مذکورہے۔ اس لیے ہم پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو بھی ہندوستانی تہذیب کے نام سے یاد کریں گے۔ پاکستان کے چاروں مراکز میں تہذیبی آثار کافی قدیم ہیں لیکن سندھ اور گندھارا (پشاور) کی تہذیبی روایت سب سے زیادہ قدیم ہیں اور پھر ان دونوں میں بھی گندھارا تہذیب یا پشتونوں کا ثقافتی ورثہ اس لیے زیادہ قدیم اور مستحکم تسلیم کیا گیا ہے کہ سندھ میں بھی پشتون تہذیب کے اثرات مختلف ادوار میں موجود نظر آتے ہیں۔ نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب، بلوچستان اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں پشتون تہذیب ہمیشہ موثر اور نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پشتون تہذیب کے اثرات ہندوستان اور پاکستان کے دوسری تہذیبوں پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ پشتونوں کے لسانی اثرات بھی پاکستان کی دوسری ثقافتوں اور زبانوں پر نمایاں ہیں۔
لسانی، سیاسی اور سماجی اثرات قبول کرنے سے پہلے ہندوستانی ثقافت نے پشتونوں کے مذہبی اثرات قبول کرلیے۔ اسلام سے پہلے ہندوستان میں ویدوں (رگ وید، اتھروید۔ بجروید اور ساماوید) کا دور تھا لہٰذا ویدوں سے افغانوں کا کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔
آریا من حیث المجوع کون تھے؟ اور ان کا اصلی وطن کون سا تھا؟ یہ واضح نہیں ۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اصل آریا افغان قبائل ہی تھے اور ان کا مسکن ہندوستان سے پہلے افغانستان ہی تھا۔ فرانسیسی مورخ ڈاکٹر گستاولی بان نے تو ان آریاوں کو پٹھان ہی کہا ہے چنانچہ وہ "تمدن ہند" میں لکھتے ہیں:
"ان اقوام کے بیان سے پہلے ہم کچھ بیان آریاوں کا کریں گے کیونکہ اگرچہ یہ تعداد میں کم ہیں لیکن اپنا اثر ڈالنے اور مذہب و زبان کے پھیلانے کے لحاظ سے ان کا بڑا درجہ ہے۔ اصلی آریا پنجاب کے شمال و غرب میں اس منفذ سے قریب ہیں جن کا نام ہم نے باب آریا رکھا ہے۔ یہ ایرانی افغان ہیں جو پٹھان کہلاتے ہیں اور درستان اور کافرستان کے باشندوں سے بہت مشابہ ہیں اور کشمیریوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے رنگ صاف، ناک خمدار، چہرے بیضاوی، بال بھورے اور بعض اوقات سفیدی مائل اور آنکھیں عموماً کنجی ہیں۔ یہ خصائص ہندیوں میں کم پائے جاتے ہیں اور جہاں اکثر بال اور آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوتی ہیں"۔ (1)
پروفیسر عبدالحئ حبیبی نے مختلف تاریخی دستاویزات کے حوالوں سے آریاوں کا وطن آریانہ ویجہ بتایا ہے اور "آریانہ ویجہ" کی لفظی ساخت کو افغان بتایا ہے:
"دریائے آمو کے شمالی کناروں اور آریانا ویجہ نامی شہر میں ۲۵۰۰ھ ق م میں یہ لوگ آباد تھے جہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا تو باختر میں آگئے اور ہندوکش کے شمال و جنوب میں آباد ہوگئے۔ یہاں سے وہ دریائے سندھ کے آس پاس رہنے لگے اور ایک تہذیبی تسلسل قائم کیا جس کو ویدی تہذیب کہتے ہیں۔ اس تہذیب کے اثرات ویدوں میں نمایاں ہیں اور ان ہی ویدوں میں افغان قبائل کا تذکرہ بھی ہے"۔(2)
جناب عین الحق فرید کوٹی نے ہندوستانی، ایرانی اور افغانی تہذیب کے ساتھ ترکمانیہ تہذیب کا ذکر بھی کیا ہے اور ان چاروں تہذیبوں کو چار ہزار سال قبل از مسیح کا قرار دیا ہے۔ وہ روسی ماہر آثاِر قدیمہ وی ایم میسن کی کتاب "روسی وسط ایشیا کا آثاراتی مطالعہ" کے حوالے سے لکھتے ہیں:
"وسط ایشیا میں حالیہ کھدائیوں کے دوران جو حقائق سامنے آئے ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی ترکمانیہ کی چار ہزار تا دو ہزار سال قبل از مسیح کی مستقل زرعی نظام کی حامل تہذیب کا اپنی ہم عصر ایرانی، افغانی اور پاک و ہندو تہذیبوں سے گہرا رشتہ تھا"۔ (3)
گریئرسن نے بھی آریائی قبائل کے مختلف جتھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ افغانستان میں رہے، لہٰذا افغانی تہذیب ہی سے متاثر ہونا ایک لازمی امر تھا۔ گریئرسن کا بیان یہ ہے:
We has seen above that the Aryans reached Persia as a united people, and that at an early period, before their language had developed into Iranian, some of them had continued their eastern progress into India. We are not to suppose that this took place all at once, in one incursion. Wave after wave advanced, the people first establishing themselves in Afghanistan, and thence, in further waves, entering India through the Kabul valley. (4)
ترجمہ:
ہم نے دیکھا کہ آریا لوگ پرشیا میں پھیل گئے۔ اس ابتدائی دور میں ان کی زبان فارسی تھی۔ بعد میں کچھ لوگ ہندوستان میں داخل ہوگئے لیکن یہ سب کچھ یک دم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہوا۔ یوں یہ آریا لوگ پہلے افغانستان میں اور پھر وادئ کابل سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے۔
یوری گنگو فسکی کا بھی یہی بیان ہے:
"امکان اس کا ہے کہ اصل ہند آریائی قبائل سندھ میں افغانستان کے جنوب مغرب اور جنوب سے درہ بولان سے ہوتے ہوئے بالائی سندھ پہنچے اور پانچ دریاوں کے دیس پنجاب درہ گومل (ژوب وادی پار کرکے) اور درہ خیبر (کابل وادی پار کرکے) سے گزر کر آئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض قبائل موجودہ افغانستان کے شمالی علاقوں سی بھی پہاڑی دروں کو پار کرکے وادی کابل سے ہوتے ہوئے پہنچے ہوں اور کچھ مزید مشرق کی طرف خیبر طے کرکے آئے ہوں"۔ (5)
غرض یہ کہ ہندووں کی مقدس کتابوں یا ویدوں کے کچھ حصے ان ہی پشتونوں کی سرزمین میں لکھے ہوئے ہیں۔ وادی سوات میں ویدی تحریروں اور آریائی تہذیب کے آثار کی موجودگی تو پہلے سے تسلیم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان قندھار میں ویدوں کی تحریر کا ذکر گریئرسن نے کیا ہے:
“The earliest documents that we possess to illustrate the language used by the Indo-Aryans of this period are continued in the Vedas, although we know that they still worshipped some gods by the same names. As those which were known to their Arian Ancestors while yet in the Manda. The hymns forming the collection known as the Vedas were composed at widely different times and in widely different localities, some in Arachosia, in what is now Afghanistan, and some in the country near the Jamna.” (6)
ترجمہ:
"ان ابتدائی دستاویزات میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہند آریائی لوگوں کی زبان ویدی ادب (رگوید) میں موجود ہے۔ ان لوگوں کے آباواجداد آریا تھے جو پہلے پہل منڈا قبائل میں شامل تھے۔ اب تک دستیاب تحریری سرمایہ میں ویدی ادب سرفہرست ہے جو مختلف ادوار میں مختلف علاقوں سے دستیاب ہوا ہے۔ اس ویدی ادب میں ہندوستانی خطے کا تہذیبی پس منظر موجود ہے۔ ان دستاویزات میں کچھ آرا کوزیا، افغانستان اور کچھ ملک جمنا میں ملے ہیں"۔
گریئرسن کے اس بیان کے ساتھ ان کے "لنگوسٹک سروے آف انڈیا" میں پروفیسر ہرٹل کے حوالے سے ایک حاشیہ میں ویدوں کی تحریر کے سلسلے میں پرشیا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو پشتونوں کا مسکن رہا ہے۔ حاشیہ یہ ہے:
“Professor Hertal maintain that the older hymns of the Rigveda were composed in Persia, before the migration of the Arians into India, and that they were sacred hymns of the Arians before the great split” (7)
ترجمہ:
"پروفیسر ہرٹل نے کہا ہے کہ کچھ پرانے نظریات ہمیں رگوید میں ملتے ہیں جو پرشیا سے دستیاب ہوئے ہیں۔ آریا لوگ مختلف قبائل میں تقسیم ہونے سے پہلے بہت اعلیٰ نسل کے لوگ تھے جب انہوں نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی نہیں کی تھی"۔
ان بیانات میں خاص بات یہ ہے کہ آرین کے ہندوستان میں وارد ہونے سے پہلے وید تحریر ہوچکے تھے اور ہندوستان میں دردر کے ساتھ وہ ویدی تہذیب جو پشتون تہذیب و تمدن اور جعرافیائی اثرات سے متاثر تھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں تک کہ افغانستان سے جانے والے لوگوں نے ہندوستان میں پہلے سے موجودہ تہذیب پر اپنے اثرات کچھ اس انداز سے مرتب کئے کہ سابقہ تہذیب تقریباً معدوم ہوگئی۔ چنانچہ فارغ بخاری نے ماہرین کی مجموعی رائے کے ضمن میں درست کہا ہے کہ:
"ماہرین کی رائے ہے کہ ہندومت میں شودیوتا کی پرستش وادی سندھ کے باسیوں کے مذہب سے لی گئی ہے۔ یہ تمدن کوئی دو ہزار سال قائم رہا۔ یہ لوگ کانسی کے ہتھیار استمعال کرتے تھے اور غالباً امن پسند تھے۔ چنانچہ جب ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح میں جنگجو آریا قوم موجودہ افغانستان سے اس برصغیر میں داخل ہوئی تو یہ لوگ ان کا مقابلہ نہ کرسکے اور تہذیب تقریباً معدوم ہوگئی"۔ (8)
اس سلسلے میں سراولف کیرو (Olaf Caroe) نے بڑی تفصیل سے ہندوستان اور موجودہ پاکستان کی قدیم آبادیوں پر پشتونوں کے لسانی اور ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا ہے وہ لکھتے ہیں:
“So far, in respect of the Afghans or Pathans in the pre-Islamic era, we have only examined the traditional sources recorded in a number of writings in Persian, drawn up at the Mughal court not earlier than the beginning of the seventeenth century. This examination has shown a well marked consciousness that these people were of at least three different stocks which have come together in juxtaposition, all speaking varieties of the same language, but, owing to a predisposition for the tribes not to mix in marriage, preserving a large number of separate tribal cells with in the hive. We have also learned much of the intertribal affinities, as these are known to the people themselves”. (9)
ترجمہ:
افغانوں اور پشتونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے دور کی قوموں میں سے ہیں۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ان کی تہذیبی دستاویزات فارسی زبان میں محفوظ ہیں جو سترھویں صدی عیسوی سے پہلے کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دستاویزات کی فائلیں عدالتی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے پہل یہ لوگ تین مختلف گروہوں میں منقسم تھے جو بعد میں ایک مرکز پر جمع ہوئے۔ یہ لوگ ایک ہی زبان مختلف لہجوں میں بولتے تھے۔ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے شادی نہیں کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ افغانستان اور پاکستان میں دریائے سندھ کے مغربی کناروں پر آباد تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کا ثقافتی ورثہ اسلام کے بعد نمودار ہوا ہو۔ اس لئے کہ اسلام سے پہلے داریوش بادشاہ کے دور میں ان کے ثقافتی اثرات فارسی زبان میں سائرس کے سلطنت میں ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں یونانی مورخین نے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کے ثقافتی اقدار کے نشانات دار یوش کے دور میں بیستون کے پہاڑوں میں ملے ہیں۔
آگے لکھتے ہیں:
“Thus the fact that Transoxiana, Afghanistan and Pakistan west of the Indus, are even now Khurasani in culture is due in the first instance not to Islamic conquests but to earlier Achaemenian, those countries. The first and most overpowering of these Persian influences was the empire of Cyrus and Darius the Great. And for that period our records, almost if not quite contemporary, are the Greek historian Herodotus and the inscriptions of Darius at Susa, at Bisitun (Behistan) and on his tomb at Naqsh-i-Rustam near Persepolis in the Persian province of Fars. (10)
یونانی (Greek) دانشور ہیروڈوٹس اور دیگر مغربی اسکالرز کے حوالے سے سراولف کیرو پشتونوں کے اوریجن (Origin) پشتو زبان کی فارسی اور ساکازبانوں سے نسبت اور تعلق اور پاکستان کی موجودہ ثقافت اور زبانوں پر اثر انداز ہونے کے بارے میں تفصیل سے لکھتے ہیں:
“Morgenstierne, the most up to date authority, is better acquainted with the Pathans in the field than any who have written with authority on their language. The candle in his tent burns as clearly as the lamp in his study. In origin, he says, Pashtu, or possible to define its relationship more closely. As such, it is both borrowed freely from the indo-Aryan group. Of these borrowings, mainly morphological, he gives important examples to which of which a knowledge enables a comparison of Pashtu and Persian words to be made. And, lastly, he refers to the two striking ‘iso-glotts’ the first the separation of the hard and soft variants of the language, and the second, cutting across that line of division, another which encircles (most significantly) all the Karlanri tribes. This is the change of a into broad o, into o or e, and of u into i.
We have to see how all this bears on the Sakas. One of the most obvious and regular phonetic changes to be observed in relating cognates in the Persian and Pakhtu is to be seen in the Persian a which becomes the Pakhtu. A few common words will serve to illustrate the point:
Persian pidar, father Pakhtu pilar
" didan, to see " lidal
" daram, I have " laram
" dab, ten " las
" dukhtar, daughter " " lur
" dast, hand " las
" diwaneh, mad " lewanay
Now the names of the Saka rulers of Gandhara are known from coins, and number of titles and technical terms are to be found in Kharoshthi inscriptions. All these names are transparently Iranian, and of the eastern group. Examples are: spalagadama (spada = army, ga diminutive, dama = leader, cf. Latin dominus); spala hura (spada = army, ahura = spirit, god, cf. Ahuramazda); chastana (cf. Pashtu chashtan, Pakhtu tsakhtan = master, husband). In a number of these will be observed the feature of l for d, a sign-manual of the Pakhtu and Pashtu language.
It is also noteworthy that the east Iranian names and titles are not limited to the Sakas, but continue into the later period of the Kushans, who succeeded them in Gandhara. The Kushans, even if they were not themselves Sakas, had many Saka subjects. The bringing in of this comparative material from Scythian coins and inscriptions seemsm to establish at least one strain in the Pakhtu language”. (11)
ترجمہ:
"مارگن سٹائرن جو زبانوں کا بہت بڑا عالم ہے، کہتا ہے کہ پشتو اور فارسی کی بنیاد ایک ہی ہے۔ یہ دونوں زبانیں انڈو آرین خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لسانی ساخت کے لحاظ سے دونوں زبانیں ایک گروہ سے متعلقہ نظر آتی ہیں۔ اگر ان دونوں زبانوں کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ ان میں کہیں کہیں لہجے کی نرمی اور سختی کا فرق نظر آتا ہے اور کچھ تہذیبی امتیاز بھی نمایاں ہے۔ فارسی پشتو کے کرلانی قبائل کے لہجے سے قریب قریب مماثلت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں زبانوں میں کافی حد تک لغوی اشتراک پایا جاتا ہے۔ فارسی میں باپ کو "پدر" جبکہ پشتو میں "پلار" کہتے ہیں۔ اسی طرح دونوں زبانوں میں بالترتیب دیکھنے کو دیدن اور لیدل ، دس کو "دہ اورلس"، بیٹی کو "دختر اور لور" ہاتھ کو "دست اور لاس" کہتے ہیں۔ یہ آثار تحریری صورت میں ساکا حکمرانوں کے دور میں خروشتی رسم الخط میں مل سکتے ہیں۔ یہ تقریباً تمام نام ایرانی اور مشرقی گروپ سی تعلق رکھتے ہیں۔ چند ایرانی قبیلے ایسے ملتے ہیں جن کو زبانوں کو پکتو اور پشتو کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ان مشرقی ایرانیوں کے نام ساکاوں سے بہت کم ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیتھین لوگوں کے دور میں کچھ سِکوں پر درج لکھائی بھی تقریباً پکتو یا پشتو زبان میں ملتی ہیں"۔
داریوش اعظم ہخامنشی دور کا بادشاہ تھا جو ایرانی تہذیب کا نمائندہ تھا لیکن اس وقت کے ایران میں بیشتر حصہ آج کے افغانستان کا بھی شامل تھا اور ایرانی تہذیب میں افغانی اثرات بھی بہت نمایاں تھے لہذا موجودہ پاکستان اور قدیم ہندوستان کے کچھ حصوں میں جب ایرانی تہذیب کا رواج تھا تو پشتون تہذیب کا عمل دخل اس میں لازمی ہونا تھا۔ اسی لئے تو فرانسیسی (French) سکالر گستاولی بان نے قدیم آریاوں کو ایرانی پٹھان کے نام سے یاد کیا ہے۔ سید سبط حسن نے یونانی سکالر ہیروڈوٹس کے حوالے سے پاکستانی تہذیب پر ایرانی اور افغانی اثرات کے بارے میں لکھا ہے:
"ہندوستانی (سندھی اور پنجابی) سپاہی سوتی وردیاں پہنے ہوئے تھے اور تیر کمان سے مسلح تھے۔ ان کے تیروں کے پھل لوہے کے تھے اور ان کا سالار ارتا باتیس کابیٹا فرناز اتھرس تھا۔ گندھارا اور ددی سائی کے پرے ارتابانس کے بیٹے ارتی فائس کی کمان میں تھے اور پاری سانی (بلوچ) سپاہ کا کماندار سیرو مترس تھا۔ یہ لوگ بھی پختائیوں (پختون) کی طرح چمڑے کی صدریاں پہنے ہوئے تھے اور تیر کمان اور خنجروں سے آراستہ تھے۔ ہندوستان سوار گھوڑوں پر یارتھیوں میں بیٹھ کر لڑتے تھے"۔(12)
اسی دور میں پاکستانی زبانوں اور پشتونوں یا افغانوں کے لسانی اثرات کے بارے میں چند حوالے دئے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مظفر حسن ملک ہیروڈوٹس کے حوالے سے لکھتے ہیں:
"اگر یہ نظریہ قبول کر لیا جائے کہ ہیروڈوٹس نے جن پکتائی قبائل کا ذکر کیا ہے، وہ پختون ہی ہیں (جدید محققین اس نظرئے کو قبول کرتے ہیں) تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ افغان قبائل ہزار سال سے ہندوستان کے شمال مغرب اور بلوچستان میں اقامت گزیں ہیں۔ اگر ان کو اتنا قدیم مان لیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ ایک زمانے میں ہندو دھرم اور اس کے بعد بدھ مت کو قبول کرچکے تھے۔ مدت تک افاغنہ کے علاقوں میں بدھ مت قائم رہا ، جس کے آثار ملتے ہیں مگر دسویں صدی عیسوی میں جس جوش و خروش سے انہوں نے اسلام قبول کیا ، اس کی مثالیں کہیں اور نہیں ملتیں"۔
رگ وید میں جن آریا قبائل کی فہرست دی گئی ہے یا ذکر کیا گیا ہے ، ان میں پکتا (پختون) اور گندھارا قبائل کا بھی نام موجود ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا بادشاہ تھا اور بادشاہی نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی تھی۔
بعض ماہرین کا خیال ہی کہ پشتو اور پشتون آریاوں کی آمد سے بھی قدیم ہیں اور ان کا مرکزی شہر باختر بابل اور نینوا کا ہم عصر ہے۔ (ا سے اب بلخ کہا جاتا ہے) داریوش کبیر کے سنگی کتبوں میں جو خط میخی میں لکھے گئے ہیں اور ۵۱۶ق م کے لگ بھگ تحریر ہوئے ہیں، ان میں سے کم از کم تین میں علاوہ اوستا کے ، پشتو عبارت بھی تحریر ہے نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ پشتو زبان اتنی قدیم ہی کہ اس کے الفاظ اور مصادر دنیا کی قدیم ترین زبانوں، اوستا، قدیم فارسی اور پہلوی اور سنسکرت میں شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آریاوں کی نقل مکانی کا قدیم ترین سلسلہ باختر میں ہی ہوا۔ یہ عمل کوئی اڑھائی ہزار سال قبل مسیح وقوع پذیر ہوا، پشتو زبان اس وقت بھی موجود تھا اور باختر کا علاقہ عہد میں بھی آباد تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پختونوں کی اپنی تاریخ ہے جو دیگر اقوام، مثلاً بابل اور نینوا کی ہم عصر ہے"۔ (13)
اکثرماہرین لسانیات پشتو کو ہند ایرانی زبان کی شاخ سمجھ کر اسے قدیم فارسی کی ایک شاخ قرار دیتے ہیں مگر ان ماہرین کی یہ رائے پشتو کو نہ سمجھنے کا شاخسانہ ہے۔ پشتو اصل میں ایک الگ زبان ہے جس کے اثرات ہندوستان کی قدیم زبانوں سنسکرت اور ژوند نے بھی قبول کئے۔ پشتون ماہر لسانیات جناب سلطان محمد صابر نے اس حوالے سے بہت قابل قدر تحقیق کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
"آریانا میں ایک زبان بولی جاتی تھی جیسا کہ استرابو نے کہا ہے اور پھر ہندی اور پاس کی جغرافیائی تقسیم اور مختلف تہذیبوں کی وجہ سے دو علیحدہ علیحدہ زبانیں بنیں یا پیدا ہوئیں جن میں ایک زرتشت کی کتاب "اوستا" کے نام سے اوستائی اور پھر پہلوی یا پارسی ہوئی اور دوسری جو آریانا کے مشرق میں پیدا ہوئی، سنسکرت کے نام سے سامنے آئی یعنی یہ دونوں زبانیں ایک بڑی زبان سے وجود میں آئیں۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ سنسکرت، اوستا یا پارسی زبانوں کی آمد سے پہلے جو زبان آریانا کے لوگ بولتے تھے اس کا نام کیا ہے۔ دوسرا یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ یہ وہ زبانیں کیوں کر اور کیسے بنیں، وہ کون سے حالات اور واقعات تھے جو ان زبانوں کے پیدا کرنے کے محرک بنے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آریا کے عین مرکز میں جو لوگ رہتے تھے وہ پشتون تھے جیسا کہ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے ۴۰۰ق م میں ان کو پکتان اور پکتولیس کے نام سے یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ جو پکتیا پکتیکا میں بستے ہیں، بڑے بہادر، دلیر اور جنگجو ہیں، چمڑے کا لباس پہنتے ہیں، تیر اور چھریاں لئے پھرتے ہیں۔ پکتیا یا پکتیکا وہ علاقہ ہے جس کو مورخین نے آرا کو زیا کے نام سے بھی بار بار یاد کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد (مرحوم) نے اپنی کتاب اصحاف کے ذوالقرنین کے حصے میں جدروشیا (بلوچستان) کا شمالی خطہ آرا کو زیا کے نام سے کیا ہے۔ بعض مورخین نی آرا کوزی کا بھی کیا ہے جو اس علاقے کا ایک بڑا قبیلہ ہے۔ ہیروڈوٹس اور استرابودےکو مورخین اور سیاحوں کے علاوہ فردوسی نے بھی اپنے شاہنامہ میں اپنے دور سےبہت پہلے کے واقعات بیان کرتے ہوئے آراکوزیا کے لوگوں کو افغان کے نام سے یاد کیا ہے۔ (14)
یہی محقق مختلف مغربی دانشوروں کے حوالے دیتے ہوئے مزید لکھتے ہیں:
"قدیم ہندی اورفارسی تہذیبوں اور مدنیتوں نے پشتونوں پر کوئی خاص اثرات مرتب نہیں کئے جبکہ ان کی زبان پرانے سیاسی اور مذہبی غلبوں سے آزاد اور محفوظ رہی ہے اور یہ وہ زبان ہے جو آریانا میں بولی جاتی تھی اور بقول "استرابو" کے آریانا کے تمام لوگ اسی زبان میں بات کرتے تھے۔ اب جب یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی ہے کہ پشتو آریانا کے لوگوں کی زبان ہےاورآریاناکے لوگ بقول "ہیروڈوٹس" ۴۰۰ ق م یعنی ڈھائی ہزار سال پہلے پشتون تھے اور "ریسک" کے شرائط کے مطابق اس زبان میں لغات بھی زیادہ ہیں اور صرف ونحو کے لحاظ سے بھی کافی وسیع اور کامل زبان ہے اور یہ بھی واضح ہوگیا ہے کہ سیاسی اورمذہبی غلبے اورتسلط کے تحت بھی نہیں آتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک وشبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ وہی پرانی آریائی زبان ہے جس سے سنسکرت اورفارسی دوبہنیں پیدا ہوئیں اور جن کا سنسکرت اور فارسی کے الفاظ اور ناموں میں اشتراک اور مشابہت دیکھا جاتا ہے اصلاً پشتو الفاظ اور نام ہیں جو دونوں زبانوں کو دیے گئے ہیں"۔ (15)
ہندوستان میں آریاوں کی ورود سے پہلے پشتونوں کی اپنی سرزمین میں موجودگی اور آریائی زبانوں پر اپنے اثرات ثبت کرنے کےلئے چند حوالے پیش کیے جاتے ہیں:
وادی سندھ کی تہذیب کو ماہرین آثار قدیمہ نے ہزاروں سال قبل مسیح کی پرانی تہذیب ثابت کیا ہے۔ رگوید میں وادی سندھ کی تہذیب کے ذکر کے ساتھ وادی پشاور کا تذکرہ بھی (گندھارا کے نام سے) موجود ہے۔ شرف الدین اصلاحی اس سلسلے میں رگوید کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں:
"رگ وید میں سبھی خاندانوں کے متعلق مذکور ہے کہ وہ پانی کی سہولت کی وجہ سے ساتوں ندیوں کے کنارے آباد ہوگئے تھے جن میں سے پانچ ندیاں پنجاب کی تھیں۔ چھٹی سرسوتی اور ساتویں سندھو۔ ان ساتوں ندیوں کو ملا کر سپت سندھ یعنی سات دریا کہتے تھے۔ جس کا تلفظ پارسیوں کی "ژنداوستا" میں ھپت ہندو ہے۔ اس میں سندھ، پنجاب اور گندھارا (موجود پشاور اور اس کے آس پاس کا خطہ) شامل ہے"۔ (16)
گندھارا کی تہذیب کا ذکر سندھ کی تہذیب کے ساتھ ہوا ہے جو آریاوں کے ہندوستان میں ورود سے پہلے ہے۔ آریاوں کا ہندوستان میں ورود جن راستوں سے ہوا ہے ان میں ایک راستہ افغانستان کا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ افغانستان اور گندھارا کے تہذیبی اثرات لیے بغیر آریا کس طرح ہندوستان میں داخل ہوسکتے تھے۔ یہی نقطہ ڈاکٹر وزیر آغا زیادہ صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں:
"آریاوں کے قافلے وسطی ایشیا سے نکل کر ایران پر قابض ہوگئے تھے۔ یہاں سے ایک طرف تو انہوں نے آرمینیا، شام اور شنار (عراق) کی جانب پیش قدمی کی (اس کا تفصیلی ذکر پہلے آچکا ہے) اور دوسری طرف افغانستان کے برصغیر میں اترتے چلے آئے۔ ہندوستان میں آریا ۵۰۰ ق م کے لگ بھگ داخل ہوئے"۔ (17)
ڈاکٹر ساجد امجد کا بیان ہے کہ:
"گویا آریا کئی مرتبہ ترک وطن کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس اثنا میں وسط ایشیا کے وسیع میدانوں میں چکر لگاتے رہے۔ دراصل آریا نسل اول اول دوشاخوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ ایک گروہ بدخشان کے نزدیک آباد تھا دوسرا بلخ کے نزدیک۔ جس زمانے میں آریاوں کے ہاں بادشاہی کا آغاز ہوا اسی زمانے کے لگ بھگ آریائی خاندان کی دو شاخوں میں وہ مذہبی تنازعہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں مشرقی شاخ اپنے مرزبوم سے جلاوطن ہوگئی۔ یہی شاخ ایران و افغانستان اور ہندوکش کے تنگ راستوں سے ہوتی ہوئی ہندوستان میں آئی اور پنجاب میں بس گئی۔ مسیح علیہ السلام سے ایک ہزار برس پہلے آریا لوگ آہستہ آہستہ ملک پنجاب میں پھیلنے لگے اور کچھ عرصہ بعد کوہ ہمالیہ سے بندھیا چل تک سارا ملک آریا ورت کہلانے لگا"۔ (18)
برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کا آغاز محمد بن قاسم کی فتح سے سندھ سے ہوتا ہے۔ شیخ محمد اکرام کی تحقیق کے مطابق:
"سندھ اور ملتان ۷۱۳ء میں فتح ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوئی ڈھائی تین سو سال تک راجپوت شمالی ہندوستان میں بے کھٹکے حکومت کرتے رہے اور باہر سے کوئی مسلمان تلوار کا دھنی ہندوستان میں نہیں آیا۔ ۹۸۰ء کے قریب امیر سبکتگین نے ہندوستان کی شمالی مغربی سرحد کی طرف نظر کی اور بعض اہم فوجی مقامات فتح کرکے آنے والوں کا راستہ صاف کیا لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ محمد بن قاسم کی مہم کی طرح اس نے بھی کسی سوچی ہوئی سکیم کے مطابق نہیں بلکہ واقعات سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا"۔(19)
یوں تقریباً تین سو سال ہندوستان پر عرب اور پھر راجپوت تہذیبوں کا اثر رہا لیکن اس کے بعد جب محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین غزنی میں تخت نشین ہوئے تو ایک بار پھر ترکوں اور افغانوں کے تہذیبی اثرات ہندوستان پر مرتب ہونےلگے۔ شیخ محمد اکرام مختلف تاریخی اسناد کی روشنی میں لکھتے ہیں:
"جب امیر سبکتگین ۹۷۶ء میں غزنی میں تخت نشین ہوا، اس وقت کابل اور پشاور کا علاقہ پنجاب کے راجا جے پال کے زیر نگین تھا۔ افغانستان میں دونوں کی سرحدیں ملتی تھیں۔ جے پال کو سبکتگین کی کشور کشائی ناگوائی ہوئی تو وہ ایک لشکر لے کر غزنی کی طرف بڑھا۔ لغمان اور غزنی کے درمیان ۹۷۹ء میں جنگ ہوئی جس میں جے پال نے شکست کھائی اور اسے صلح کے لیے ملتجی ہونا پڑا۔ سبکتگین کا بیٹا محمود جو اپنے باپ کے ہمر کاب تھا، صلح کے خلا ف تھا لیکن جب جے پال نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت، نقد و جنس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھ سے فناکرکے بے جگری سے لڑتے ہیں تو محمود بھی خاموش ہوگیا"۔ (20)
سبکتگین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حکومت شروع کی۔ اس سلسلے میں شیخ محمد اکرام آگے لکھتے ہیں:
"سبکتگین نے ۹۹۷ء میں وفات پائی اور اس کی جگہ محمود تخت نشین ہوا جس کی فتوحات کا سلسلہ سکندر اعظم کی یاد دلاتا ہے۔اس نی جے پال کے خلاف لڑائی جاری رکھی اور ۱۰۰۱ء میں اٹک کے قریب اسے شکست دی۔ جے پال کے بعد اس کا بیٹا انند پال تخت نشین ہوا۔ اس نے بے سمجھی سے ۱۰۰۵ء میں جب محمود ملتان کے اسمٰعیلی حاکم ابوالفتح داود کے خلاف انتقامی کاروئی کر رہا تھا، محمود پر حملہ کردیا لیکن شکست کھائی اور کشمیر بھاگ گیا۔ اگلے سال محمود نے انند پال کو "مخالفت کی مزید سزا" دینے کا ارادہ کرلیااور پشاور کے قریب اس کے عظیم لشکر کو شکست دے کر ہندوستان میں داخل ہوا اور کانگڑہ تک چڑھ آیا۔ اس کے بعد اس نے ہندوستان پر کئی حملے کیے اور متھرا، قنوج اور سومنات وغیرہ سے بہت سامالِ غنیمت لے کر واپس آیا۔ محمود نے ان مقامات پر کوئی حکومت قائم نہ کی لیکن اخیر میں لاہور کی حکومت اپنے غلام ایاز کو دے گیا۔ محمود نے ۱۰۳۰ء میں وفات پائی"۔ (21)
اس کے بعد ہندوستان پر غوری، خلجی، تغلق اور لودھی خاندانوں کی حکمرانی رہی جو تمام افغانی تھے، خلجیوں اورتغلقوں کو ترک نسلوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن وہ افغانی تہذیب ہی کو ہندوستان میں لائے تھے۔ اس سلسلے میں جناب فارغ بخاری مزید رہنمائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"ہندوستان میں مغلوں سے پہلے جتنی مسلمان حکومتیں گزریں وہ سب افغان تھیں۔ سوری، لودھی، خلجی حتٰی کہ سادات کے متعلق بھی فرشتہ کا کہنا ہے کہ وہ افغان ہی تھے جو بعد میں سادات بن بیٹھے۔ باقی رہا خاندان غلاماں سو وہ بھی افغانوں ہی کے غلام تھے۔ لودھیوں کے دور میں اندرونی اختلافات کی وجہ سے افغان سرداروں نے سازش کرکے بابر کو بلایا۔ اس وقت افغانستان بابر کے تسلط میں آچکا تھا۔ اس کی کابل سے محبت اس وصیت سے ظاہرہے کہ مرنے کے بعد اس نے کابل میں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ادھر بابر نے فوج کشی کی تو اس کے ہمراہ زیادہ تر افغانی فوج ہی تھی۔ مختصر یہ کہ پنجاب اور ہندوستان پر روزاول ہی سی افغان مکمل طور پر چھائے رہے۔ ان کا عہد ختم ہوگیا تو بھی مغلوں کے دور میں افغانوں ہی کا دورہ رہا کیونکہ فوجی طاقت افغانوں ہی کے ہاتھ میں تھی۔ افغانوں کے اسی غلبے سے مجبور ہر کر بابر نے ان کی بیشتر روایات کو اس طرح قائم رکھا"۔ (22)
ہندوستان میں سبکتگین اور محمود غزنوی کے دور حکمرانی میں افغانی مع اپنی تہذیب کے موجود تھے۔ اسی دور میں قندھار و غور سے لے کر ملتان و سندھ تک پہاڑی علاقوں میں افغانی بستے تھے۔ چنانچہ البیرونی نے بھی لکھا ہے کہ:
"ہندوستان کے پچھم (مغرب کے پہاڑوں) میں مختلف افغانی قبیلے رہتے ہیں جن کا سلسلہ ملک سندھ کے قریب ختم ہوتا ہے"۔ (23)
البیرونی کی تائید میں چند دیگر حوالے بھی حافظ محمود شیرانی نے نقل کیے ہیں لیکن خلجیوں کو انہوں نے افغانیت سے خارج کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
"افغان ہندوستان کے مغرابی پہاڑوں میں دریائے سندھ تک آباد تھے۔ البیرونی ایک مقام پر ان کو افغانوں کے نام سے یاد کرتا ہے، دوسرے مقام پر ہندو لکھتا ہے۔ ابوالفرج رونی افغانوں اور جاٹوں کو مشترک کہہ رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہے افغان ان ایام میں تابع اسلام نہیں تھے۔ سیاسی اعتبار سے افغان ہر زمانے میں اہمیت رکھتے تھے۔ سلطان محمود نے دو مرتبہ ان کو گوشمالی کی ہے۔ مسعود شہید نے ان کے خلاف فوج بھیجی ہے۔ مسعود ثالث نے بھی ان کو سزا دی ہی لیکن ہندوسان میں اگرچہ فوجوں میں ہمیشہ بھرتی ہوتے تھے، تغلقوں کے عہد میں وقعت حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ خلجیوں کی طرح افغان بڑی تعداد میں ہندوستان کی طرف ہجرت نہیں کرتے تاہم ایک معتدبہ تعداد ان کی ہر زمانے میں یہاں موجود رہتی ہے۔ دہلی سے چار کوس کے فاصلے پر افغان پورا ایک قصبہ تھا جو غلاموں کے زمانے میں آباد ہوا تھا اور اس میں افغان ہی آباد تھے"۔ (24)
حافظ محمود شیرانی ہندوستان میں افغانوں کی پہلی حکومت دکن کے بہمنی خاندان کی حکمرانی کو مانتے ہیں ۔ ان کا بیان ہے:
"محمد تغلق کے آخر زمانہ سلطنت میں امیران صدہ نے دکن میں بغاوت کردی۔ موت نے بادشاہ کو اتنی مہلت نہ دی کہ باغیوں کی سرکوبی کرتا۔ ۷۴۸ھ میں حسن گنگوہ علاء الدین شاہ کے نام سے بادشاہ دکن بن گیا اور تقریباً دو سو سال تک بہمنی خاندان دکن میں حکومت کرتا رہا اور ۹۳۳ھ میں ختم ہوا۔ یہ پہلا افغان خاندان ہے جو ممالک ہند میں سریر آرا ہوتا ہے۔ بہمنیوں کی میراث پانچ سلطنتوں میں منقسم ہوجاتی ہے۔ (۱) عماد شاہی جسے ۹۸۰ھ میں نظام شاہی برباد کرتے ہیں۔ (۲) نظام شاہی جنہیں اکبر کی فوجیں ۱۰۰۴ھ میں فتح کرلیتی ہیں۔ (۳) برید شاہی جو ۱۰۱۸ھ تک حکمرانی کرتا ہے۔ (۴) قطب شاہی ۱۰۹۸ھ میں عالمگیر ان کا علاقے اپنی قلمرو میں شامل کر لیتا ہے جو سلطنتیں ان میں طاقتور اور ممتاز تھیں اور جن کے زمانے میں اردو ادبیات کو فروغ ہوتا ہے ۔ قطب شاہی اور عادل شاہی ہیں"۔(25)
سعود الحسن خان، حافظ رحمت خان کے خلاصتہ الانساب کے حواشی میں لکھتے ہیں:
"محمود غزنوی کی زیادہ فوج ترکوں اور پٹھانوں پر مشتمل تھی، العتبی نے بھی ایسا تحریر کیا ہے۔ ابتدائی چند حملوں میں اسے ناکامی ہوئی مگر بعد میں کامیابی ہوئی۔ پٹھانوں پر مشتمل اس کی فوج اس کے ترک فوجیوں کی نسبت زیادہ موثرتھی۔ (26)
ڈاکٹر وزیر آغا ہندوستان پر محمد بن قاسم کے بعد افغانوں کے حملوں کو تہذیبی یلغار کا نام دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:
"وہ تہذیبی یلغار جو نتائج کے اعتبار سے آریاوں کی ہم پلہ قرار پاسکتی ہے، مسلمانوں سے متعلق ہے۔ مگر مسلمان بھی اسی برصغیر میں دو واضح لہروں کی صورت میں آئے۔ پہلی لہر محمد بن قاسم کی فتح سندھ کی صورت میں اور دوسری شمال کی طرف سے افغانوں کے حملے کی صورت میں"۔ (27)
شہاب الدین غوری، شیر شاہ سوری اور پھر احمد شاہ ابدالی کے دور تک وقفے وقفے سے پشتون ہندوستان پر چھائے رہے اور اپنی تہذیب سے ہندوستان کو متاثر کرتے رہے۔ ان سب ادوار کا مختصر طور پر ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
"تاریخ شاہد ہے کہ پنجاب و سرحد کے علاقے ہی وہ علاقے ہیں جو ہمیشہ سے فاتحین برعظیم کی گزرگاہ رہے ہیں اور یہی وہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کا واسطہ سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی سطح پر یہاں کے باشندوں سے پڑا جن میں بودھوں اور ہندووں کے علاوہ دوسری اقوام بھی شامل تھیں۔ اہل اسلام سندھ میں پہلی صدی ہجری میں آگئے تھے لیکن مسلمانوں کی آمد کا اصل و حقیقی راستہ یہی تھا جس کے اثرات اس برعظیم کی آئندہ تاریخ پر گہرے پڑے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں دو تہذیبیں، دو تمدن اور دو عقیدے ایک دوسرے سے ملے اور پھر یہ اثرات سارے برعظیم میں پھیل گئے۔۳۷۸ھ/ ۹۷۷ء میں جےپال کے حملے کے جواب میں حملہ کیا اور اسے شکست دے کر لغمان سے پشاور تک کے علاقے پر قبضہ کرکے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ سلطان سبکتگین کے بعد محمود غزنوی نے۳۹۰ھ/ ۱۰۰۰ء اور پھر۳۹۱ھ/ ۱۰۰۱ء میں حملہ کرکے پنجاب کو فتح کیا اور۴۰۵ھ/ ۱۱۹۲ء تک آل غزنہ یہاں حکومت کرتے رہے۔ دیسی باشندوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہیں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ایک کثیر تعداد میں "ترک، ایرانی اور دوسری مسلم اقوام بھی سب سے پہلے اسی علاقے میں آکر مستقلاً آباد ہوئیں"۔ (28)
سید سبط حسن لکھتے ہیں:
"پنجاب، سرحد اور سندھ دہلی کے مطیع تو ہوگئے لیکن غزنوی اور غوری دور کے افغان امرا اور سالارانِ فوج کےاثرورسوخ میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہ اس علاقے کی سیاسی اہمیت کم ہوئی۔ اولاً ترکی امرا کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ لہذٰا سلاطین وقت کو پنجاب اور سرحد کے ذی اثر اشخاص کو نظم و نسق میں شریک کرنا پڑتا تھا۔ دوئم سلطان محمود غزنوی اور سلطان محمود غوری کے زمانے ہی سے شاہی فوجوں میں پٹھانوں بالخصوص خلجیوں کی بڑی پیمانے پر بھرتی کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا لہذٰا سلطنت کے تحفظ اور توسیع کا انحصار پٹھان سپاہیوں کی کارکردگی پر تھا۔ وہ افغان سالار بختیار خلجی ہی تھا جس نے اودھ، بہار اور بنگال کو دہلی کی قلمرو میں شامل کیا (۱۱۹۹ء۔۱۲۰۶ء) اور وہ بھی خلجی سردار تھا جس نے خاندان غلاماں کے بعد دہلی میں خلجیوں کی حکومت قائم کی۔ اسی طرح لودھی اور سوری خاندان کے حکمراں بھی افغان تھے"۔ (29)
لودھی اور سوری دور میں پاک وہند میں پشتون تہذیب کا اثر بالکل ختم ہوگیا۔
"لودھیوں اور سوریوں کے عہد میں جو پٹھان گھرانے ہندوستان کے مختلف حصوں میں آباد ہوئے ان کی سماجی اور اقتصادی حیثیت بہتر ضرور ہوئی مگر ایک دو نسلیں گزرنے کے بعد اب کے تعلقات سرحد سے بالکل ٹوٹ گئے اوروہ اپنے تہذیبی ورثے سے بھی محروم ہوگئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے پشتو زبان بھی ترک کر دی اور ہندی و فارسی بولنے لگے اور ان کے اور شمالی ہند کے باشندوں کے رہن سہن میں چنداں فرق نہ رہا۔ دہلی، مراد آباد، فتح گڑھ، باندرہ، بریلی، رام پور، شاہجہاں پور، بھوپال، ملیح آباد کے پٹھانوں اور سرحد کے پٹھانوں میں کوئی قدر مشترک باقی نہ رہی"۔ (30)
اس دور میں مغل تہذیب نے ترقی کی اور پھربعد میں مغل حکمرانوں نے پشتون ثقافت کو مٹانے کی بہت کوششیں بھی کی ہیں۔ یہاں تک کہ مغل اور پشتون ایک دوسرے کے بدترین دشمن ثابت ہوئے۔
"مغلوں سے ہندوستانیوں بالخصوص پٹھان سرداروں کی نفرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ منگول حملہ آور دو ڈھائی سو سال سے ان کے علاقوں کو تخت و تاراج کرتے چلے آرہے تھے۔ ان کو چنگیزی اور تیموری لشکروں کی سفا کیاں نہیں بھولی تھیں اور چونکہ بابر کا تعلق بھی اسی خانوادے سے تھا لہذا لوگ بابر کو بھی غاصب اور لٹیرا سمجھتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ ہمایوں اور اکبر کے عہد میں بھی کم از کم پٹھان سرداروں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ بادشاہوں نے پٹھان سرداروں پر کبھی بھروسہ کیا۔ چنانچہ اکبر کے سترہ وزیروں، پندرہ بخشیوں اور آٹھ صدور میں ایک بھی پٹھان نہ تھا۔ (حالانکہ اس نے راجپوتوں سے میل کرلیا اور ان سے رشتہ داریاں بھی قائم کرلی تھیں) اسی طرح سلطنت کے ۴۱۲ منصب داروں میں پٹھان کل ۹ تھے۔ وہ بھی نیچے درجے کے۔ ان میں پانچ ہزاری یا تین ہزاری ایک بھی نہ تھا۔ سرحد کے پٹھانوں کی بغاوت تو اکبر کے بعد جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب کے عہد میں بھی برابر جاری رہی"۔ (31)
سبط حسن آگے لکھتے ہیں:
"مغلیہ تہذیب کی معاشی اساس پٹھانوں کے دور سے چنداں مختلف نہ تھی بلکہ اسی کی ترقی یافتہ شکل تھی۔ مغلیہ تہذیب نہ تو کسی سماجی انقلاب کا نتیجہ تھی اور نہ کسی سماجی انقلاب کی نقیب۔ مغلوں کی آمد سے نہ پیداوار کے آلات واوزار بدلے اور نہ طبقوں کے توازن میں کوئی فرق آیا بلکہ تہذیبی امتزاج کا وہ عمل جو تیرھویں صدی میں شروع ہوگیا تھا، کچھ عرصہ کےلیے رک گیا۔ پٹھانوں کے عہد میں مقامی، ترکی اور ایرانی تہذیبوں کے میل سے ایک نئی تہذیب رفتہ رفتہ ابھرتی جارہی تھی اور فارسی کی جگہ ہندوی اور دوسری علاقائی زبانوں کو فروغ ہو رہا تھا۔ (سلاطین دہلی کے پرچم پر ہلال اور مچھلی کا نشان اس تہذیبی امتزاج کی نمایاں علامت تھی) مگر ہمایوں کے ہمراہ آنے والے ایرانی امیروں اور لشکریوں کی وجہ سے ملک پر ایک بار پھر ایرانی تہذیب کا غلبہ ہوگیا۔ خود بابر، ہمایوں اور فرغانہ سے ان کے ساتھ آنے والے خاندانوں پر بھی ایرانی تہذیب ہی کا رنگ چڑھا ہوا تھا اس لیے انہوں نے بھی ایرانی تہذیب ہی کو رواج دیا۔ پٹھانوں کے عہد میں دفتری لکھا پڑھت فارسی اور ہندوی میں یا مقامی زبانوں میں ہوئی تھی۔ مغلوں نے ہندوی اور مقامی زبانوں کا استعمال ممنوع کر دیا۔ (32)
اکبر کے دور میں صوبہ سرحد کا نامور عالم پیر روشن خاص اہمیت کے حامل ہیں جن کے تصوف، ادب اور موسیقی کے اثرات نے پاکستانی تہذیب کو بہت متاثر کیا۔
"پیر روشن کی تاریخی عظمت کا جائزہ مغلوں اور پٹھانوں کی دیرینہ عداوت کی روشن میں لینا چاہیے۔ پٹھانوں نے مغلوں کی اطاعت دل سی کبھی قبول نہیں کی تھی بلکہ جہاں اور جب بھی موقع ملتا تھا، بغاوت کردیتے تھے۔ اسی بنا پر مغل پٹھانوں پر بالکل اعتبار نہیں کرتے تھے اور ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ پیر روشن کی تحریک اپنی تمام مذہبی رنگ آمیزیوں کے باوصف سرحد کے عوام کی پہلی آزادی کی تحریک تھی۔ اس کی نوعیت گجرات، مالوہ، سنبھل، جونپور، پٹنہ اور بنگال کے پٹھان سرداروں کی بغاوت سےاس وجہ سے مختلف تھی کہ موخرالذکرعلاقوں کے پٹھان سردار اپنی ذاتی ریاستوں کی خودمختاری کے لیے لڑتے تھے جبکہ پیر روشن کی جنگ سرحد کے پٹھانوں کی عوامی جنگ تھی۔ پیر روشن کا مقصد پٹھان علاقوں سے مغل اقتدار کو ختم کرنا تھا تاکہ پٹھان قبائل ماضی کی مانند آزاد اور خودمختار زندگی بسر کرسکیں۔
پیرروشن بڑے عالم اور صاحبِ کمال بزرگ تھے۔ ان کو فارسی، عربی، ہندی اور پشتو چاروں زبانوں پر پورا عبور تھا۔ وہ فلسفہ اور دیگر علوم عقلی پر بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ خیرالبیان ان کی مشہور تصنیف پشتو میں ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے شریعت اور طریقت کے مسائل پر بحث کرنے کے علاوہ پٹھانوں کے سیاسی اور قبیلہ داری اتحاد پر بھی زور دیا ہے۔ ان کی مقبولیت کا بڑا راز یہ تھا کہ وہ اپنے عقائد کی تبلیغ پٹھانوں میں پشتو زبان میں، فارسی دانوں میں فارسی زبان میں اور ہندووں میں ہندی زبان میں کرتے تھے۔ ان کے پشتو ادب اور موسیقی میں بھی پیر روشن نے اپنی نثری تصنیفات کے ذریعے پشتو ادب کی بڑی خدمت کی ہے اور ایک نئے مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی ہے۔ ان سے بیشتر پشتو زبان میں قصیدہ، غزل، قطعات اور مثنویوں کا رواج نہ تھا۔ پیرروشن نے ان تمام اصناف ِ سخن میں پشتومیں اشعار کہے۔ پیرروشن کو سماع کا بھی شوق تھا اور کہتے ہیں کہ انہی کی صحبت میں اور انہی کی ہدایت سے پٹھان موسیقار دھنا سری، پنج پردہ، چہار پردہ، سہ پردہ، جنگی آہنگ اور مقامِ شہادت کے نغمے بجانے لگے۔ (33)
لودھی، غوری، خلجی، سوری خاندانوں کی ہندو پاک پر حکمرانی کرنے سے تہذیبی ولسانی اثرات کا کافی غلبہ رہا لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ہندو پاک پر مغل تسلط آنے سے پشتون تہذیب کے اثرات ختم ہونے لگے جو نادرشاہ افغانی کے حکمران بننے سے پھر تازہ ہوگئے۔ سعود الحسن صاحب نے لکھا ہے:
"روہیلوں کی آمد کے ساتھ اس علاقے میں پٹھانوں کی آبادکاری تیز ہوگئی۔ سب سے پہلے آبادکاری بلاس پور میں بیان کی جاتی ہے۔ اس علاقے میں آباد روہیلوں کی روایات کے مطابق بھی یہاں پر روہیلے اٹھارھویں صدی کے ربع اول (۱۷۰۱ء تا ۱۷۲۵ء) میں آباد ہوئے۔ ان کا تعلق داود خان کے گروہ سے تھا۔ یہیں پر ایک مقبرہ یا سمادھی ہے۔ روایت ہے کہ یہاں کا راجہ کھیم کرن فوت ہوا اس کی بیوہ اس کی چتا پرزندہ جل مری، اسے 'ستی' کی رسم کہتے ہیں۔ داود خان نے ان دونوں کی یاد میں اس پر سمادھی کی یادگار بنادی۔ داود خان سے اس عمارت کو منسوب کرنا کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ داود خان بہت عرصہ تک ان علاقوں میں مختلف راجاوں کا ملازم بھی رہا تھا۔ وہ شاہ آباد کے راجہ مدھکر کے ہاں ہی سے پہلے ملازم ہوا تھا اور کافی عرصہ یہیں رہا۔ علاوہ ازیں افغانوں میں بھی عورتوں کے شوہروں سے وفادار نہ رہنے اور طلاق مانگنے سے نفرت کرنے کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے جو آج بھی قبائلی علاقوں میں موجود ہے۔ یوں اس واقعہ سے داود خان کا متاثر ہونا فطری امر ہے۔ روہےلوں کے ابتداءی دور میں شاہ آباد اور رام پوردونوں موجود تھے۔ رام پور کا پورا نام "رام پورہ" تھا جو چار دیہاتوں کا مجموعہ تھا۔ اس کے راجہ کا نام رام سنگھ تھا جس کا صدر مقام موجودہ رام پور کا محلہ راج دوارہ تھا۔ اسی کے نام سے اس قصبہ کا نام بھی رام پورہ تھا جو بعد میں رام پور ہوگیا۔ شاہ آباد میں سردار داود خان کے پاس بطور جاگیر بھی رہا تھا۔ علی محمد خان نے کچھ عرصہ رام پور میں بھی قیام کیا۔ اس کے دور میں ہندواورمسلمان دونوں ہی اس علاقے میں آباد ہوتے رہے جس سے روہیلوں کی مذہبی رواداری کا پتہ چلتا ہے۔ مان خان روہیلہ، اکبر خان روہیلہ اور بشارت خان روہیلہ نامی پٹھانوں نے اپنے ناموں سے کئی قصبے آباد کیے جو مان پورہ (قائم شدہ ۱۷۴۰ء) اکبر آباد اور بشارت نگر کہلاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے روہیلوں کو ان علاقوں میں آبادکاری کا حوصلہ ہوا۔ ۱۷۵۰ء میں ہی رسول پورآباد کیا گیا۔ ملک اسد اللہ پوری کی آبادکاری بھی اٹھارھویں صدی میں ہوئی۔ روہیلوں کے عہد میں ہی ایک مقامی راجہ مہتاب سنگھ نے مہتوش نامی دیہات آباد کیا۔ سیوا سنگھ نے ۱۷۵۵ء میں قصبہ سور آباد کیا۔ پانڈوناتھ مل نے ۱۷۷۵ء میں رانجھا گاوں آباد کیا"۔ (34)
یوں تو ہندوستانی تہذیب اورادب پرافغانوں کے اثرات عرصہ قدیم سے ہیں۔ ویدی عہد سے لے کر موجودہ عصر تک ہندوستان کا ادب کسی بھی دور میں پشتونوں کے اثرات سے خالی نہیں رہا۔ احمد شاہ ابدالی کے دور کے بعد تو پشتون تہذیب وتمدن نے ہندوستانی ادب میں اپنی جڑیں پھیلادیں کہ ہندوستان میں پشتو زبان وادب کے مراکز قائم ہوئے جن سے ہندوستانی ادب کا متاثر ہونا ایک فطری امر تھا۔ رام پور نجیب آباد، مراد آباد، بجنورپور، بریلی وغیرہ میں تو براہ راست پشتو زبان وادب کی ترویج ہوتی رہی۔ ٹونک فرخ آباد، روہیل کنڈ، پشتو ادب کے زیر اثر رہے لیکن پشتون اہل قلم کے علمی و ادبی مرکز کی حیثیت رام پور ہی کو حاصل رہی۔ رام پور میں یہی روہیلے تھے جو دیگر پشتون قبیلوں کو ساتھ لے کر علم و ادب کی خدمت کرتے تھے۔ رام پور میں روہیلوں کی آبادکاری کے بارے میں سعود الحسن صاحب لکھتے ہیں:
"رام پور میں پٹھانوں کی آبادی کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہاں پر پٹھان ۱۷۷۴ء میں اس وقت آباد ہوئے جب ریاست کا قیام عمل میں آیا مگر یہ عام خیال ہے، یہاں پر پٹھان شروع سے آباد ہوتے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ داود خان اوراسکا گروہ جس میں حافظ رحمت خان کے رشتہ دار بھی شامل تھے، وہ لوگ اٹھارھویں صدی کے ربع اول (۱۷۰۱ء تا ۱۷۲۵ء) میں اسی علاقے میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ راجہ مدھکر کا آبائی علاقہ ریاست رام پور کی حدود میں آج بھی موجود ہے۔ جہاں شروع میں داود خان ملاز رہا ہے۔ بلاس پور ضلع رام پور میں پٹھانوں کے کچھ خاندان ہیں۔ ان میں یہ روایت آج تک موجود ہے کہ ان کے اجداد داود خان کے گروہ سے تھے جو کہ یہاں پر اٹھارھویں صدی کے شروع میں آباد ہوگئے تھے۔ اسی جگہ پر کھیم کرن اور اس کی بیوی کی سمادھی بھی ہے جس کے بارے میں علاقے میں مشہور ہے کہ یہ داود خان نے تعمیر کرائی تھی۔ شاہ آبادضلع رام پور ۱۷۳۳ء میں ہی علی محمد خان کی زرخرید جاگیر میں تھا۔ اس جاگیر سے داود خان بھی وابستہ رہا تھا۔ ریاست کے حکمرانوں کی روایت کے مطابق ۱۷۷۴ء تک یہ نواب فیض اللہ کی جاگیر کا صدر مقام رہا اور ۱۷۷۴ء سے ۱۷۷۵ء تک ریاست رام پور کا صدر مقام بھی۔ ضلع رام پور (سابقہ ریاست رام پور) میں پٹھانوں نے ۱۷۴۰ء تک اپنے مندرجہ ذیل قصبے بسائے تھے۔ مانپور، اکبرآباد، بشارت نگر۔ ۱۷۵۰ء میں رسول پور آباد کیاگیا ۔ اٹھارھویں صدی میں ہی ملک اسد اللہ پور بھی بسایا گیا"۔ (35)
پاکستان کے تہذیب و ثقافت اور زبانوں پر پشتونوں کے یہ اثرات مختلف اوقات میں رہے ہیں۔ نہ صرف تہذیبی ولسانی بلکہ پاکستان کی فنی تعمیر، موسیقی اور دیگر فنون او ثقافتی اقدار میں بھی یہ اثرات قائم و دائم رہے۔ یہاں تک کہ فن تعمیر کے سلسلے میں جو اثرات مغلوں کے باقی ہیں ان میں بھی پشتونوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ سبط حسن نے درست لکھا ہے کہ:
"مغلوں کا فن تعمیر ان کے پیش رو پٹھانوں کے آخری دور کے فن تعمیر کی ترقی یافتہ شکل ہے البتہ مغلوں نے نئی نئی جدتیں پیدا کرکے اس فن کو کمال تک پہنچا دیا۔ پٹھانوں اور مغلوں کی عمارتوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ مثلاً اونچے اونچے محراب درمحراب دروازے، مورچہ بند منڈیریں، مرتفع کرسی، گنبد اور مینار، سنگِ مرمر کی جالیاں اور کاشی کے نقش و نگار وغیرہ مگر فرق یہ ہے کہ پٹھانوں کی عمارتیں سادہ، ٹھوس اور بھری بھر کم ہوتی تھیں اور شکوہ و جلال کا تاثر پیدا کرتی تھیں۔ اس کے برعکس مغلیہ عمارتوں کی امتیازی شان اس کا حسن ترتیب وتناسب، خوش نمائی، نفاست اور نزاکت ہے۔ اس کے علاوہ مغل کشادہ تناظر کو عمارت کا لازمی جُز قرار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر عمارت کے چاروں طرف وسیع، عریض صحن اور باغ ضرور ہوتے تھے"۔ (36)
حوالہ جات
۱۔ گستاولی بان، ڈاکٹر، تمدنِ ہند، ترجمہ از سید علی بلگرامی، مقبول اکیڈمی، لاہور، ۱۹۶۲ء،ص:۱۴۹
۲۔ حبیبی، عبد لحئی، پروفیسر، داافغانستان لینڈ تاریخ (پشتو)، دانش کتاب خانہ، پشاور ۱۳۷۸ء، ص:۹
۳۔ عین الحق، اردو میں زبان کی قدیم تاریخ، عزیز بک ڈپو، لاہور، ۱۹۹۶، ص: ۲۴۹
4. Grierson, (GA), Linguistic Survey of Pakistan, v.1 Accurate Printers, Lahore-Pakistan, p. 115.
۵۔ گنگوفسکی، یوری، پاکستان کی قومیتیں، ترجمہ از مرزا اشفاق بیگ، دارالاشاعت ترقی، ماسکو، ۱۹۷۶ء، ص: ۵۳
6. Grierson (GA), Linguistic Survey of Pakistan, V.i, p. 115
7. ……..do………….., p. 115
۸۔ بخاری، خیال، تاریخ ابیات مسلمانانِ پاک وہند، مرتبہ سید فیاض محمود، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۷۱ء، ص:۲۱۱
9. Olaf Caroe, the Pathan, p. 25
10. ………..do ……….., p. 27
11. ………..do ……….., p. 66-68
۱۲۔ حسن، سبط، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، ص: ۱۰۹
۱۳۔ ملک، مظفر حسین، ڈاکٹر، نسلیاتِ پاکستان، مقتدرہ قومی زبان، پاکستان، ۲۰۰۳ء، ص:۲۸۱۔۲۸۲
۱۴۔ شبیر، سلطان محمود، قدیم پشتو اور پشتون، ترجمہ ازعبدالفتح، پشتو اکیڈمی، کوئٹہ۔ بلوچستان، جون ۱۹۷۷، ص:۹
۱۵۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۱۴۔۱۵
۱۶۔ اصلاحی، شرف الدین، اردوسندھی کے لسانی روابط، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، مارچ ۱۹۸۷ء، ص: ۸،۹
۱۷۔ آغا، وزیر، اردو شاعری کا مزاج، مکتبہ عالی، لاہور، ۱۹۷۸ء، ص: ۶۵
۱۸۔ امجد، ساجد، ڈاکٹر، اردو میں شاعری پر برصغیر کے اثرات، غضنفر اکیڈمی، پاکستان، کراچی، ۱۹۸۹ء، ص: ۲۸
۱۹۔ اکرام، شیخ محمد، آب کوثر، ادارہ ثقافتِ اسلامی، لاہور، جنوری ۲۰۰۰ء، ص: ۵۵
۲۰۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۵۵،۵۶
۲۱۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۵۹،۶۰
۲۲۔ بخاری، فارغ، ادبیاتِ سرحد، بارِسوم، نیا مکتبہ، پشاور، ۱۹۵۵ء، ص: ۳۳
۲۳۔ البیرونی، کتاب الہند، ترجمہ ازسید اصغر علی، جلد اول، انجمن ترقی اردو ہند، دہلی، ۱۹۴۱ء، ص:۲۷۷
۲۴۔ شیرانی، حافظ محمود، پنجاب میں اردو، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۸۸ء، ۵۶۔۵۷
۲۵۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۶۱۔۶۲
۲۶۔ سعودالحسن خان، خلاصتہ الانساب، مترجم رحمت خان، افغان ریسرچ سنٹر، لاہور، دسمبر ۲۰۰۲ء، ص: ۱۲۸۔۱۲۹
۲۷۔ آغا، وزیر، ڈاکٹر، اردو کا تہذیبی پس منظر، جلد اول، فیڈرل گورنمنٹ سرسید کالج، راولپنڈی، مئی ۱۹۸۱ء، ص: ۲۳۸
۲۸۔ جالبی، جمیل، ڈاکٹر، تاریخ ادب، جلد اول، مجلسِ ترقی ادب، لاہور، جولائی ۱۹۷۵ء، ص: ۵۹۵
۲۹۔ حسن، سبط، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، ص: ۱۹۵
۳۰۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۲۰۷
۳۱۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۲۷۷۔ ۲۷۸
۳۲۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۲۸۲۔۲۸۳
۳۳۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۳۱۲۔۳۱۴
۳۴۔ روہیلہ، سعود الحسن خان، رام پور، تاریخ و ادب، ص: ۱۸۔۱۸
۳۵۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، ص: ۲۱
۳۶۔ حسن، سبط، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، ص: ۵۸۔۳۵۷