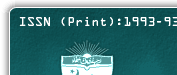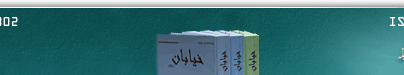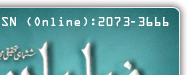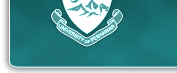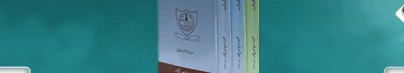منظوم ترجمے کے مسائل
[ مشرقی زبانوں کے باہمی تراجم کی روشنی میں]
ڈاکٹر ارشد محمود ناشادؔ
ایسوسی ایٹ پروفیسر(اُردو)علّامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی، اسلام آباد
ABSTRACT:
It is a universal truth that every language has its own flavor and linguistic features peculiar to itself. This peculiarity can’t be transformed in any other language. That is why translation is not an alternate to creation. But at the same time, translation has its own existence. A sufficient knowledge of the source text and target text and of the subject matter is suffice for technical and scientific texts, but to translate literary or creative writing is very complex phenomenon. The process of versified translation Is much more complex. The first and foremost condition for versified translator is that he himself should be a poet. He should be well versed in prosody also. Moreover, the translator should try to comprehend the mental sphere of the poet in totality. The present article discusses in detail the issues involved in versified translation. It also discusses the role of inter translation among oriental languages |
.
ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ایک زبان کی لغت کو دوسری زبان کی لغت میں منتقل کرناہے۔ انگریزی زبان میں ترجمہ کے لیے Translation کا لفظ مستعمل ہے، جس کے معنی’’پار لے جانا‘‘ کے ہیں۔گویا ترجمہ ایک زبان کے متن کو بہ تمام وکمال دوسری زبان کے قالب میں ڈھالنے کا عمل ہے۔ایک زبان سے دوسری زبان میں نقلِ کلام یا ایک زبان کے سرمائے کومہارت کے ساتھ’’پار لے جانے ‘‘کا عمل حد درجہ مشکل اور کٹھن ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان منفرد لسانی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے اور اس کا مزاج اور رنگ وآہنگ دوسری زبانوں سے قطعی مختلف اور الگ ہوتا ہے۔اس لیے بنیادی زبان(Source Language ) اور ہدفی زبان(Target Language ) دونوں پر قدرت رکھنے کے باوجود مترجم ایک زبان کے متن کو دوسری زبان کے قالب میں مکمل طورپر نہیں ڈھال سکتا۔ حزم واحتیاط اور کوششِ بسیار کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے اور اصل تخلیق کا کوئی نہ کوئی پہلو ترجمے کے عمل میں نظر انداز ہو جاتا ہے۔شاید اسی لیے ترجمہ،عمدہ تخلیق یا تخلیق کا کامل نعم البدل نہیں بن سکتا ۔مترجم سے اس بات کی توقع رکھنا یا تقاضا کرنا کہ اس کے ترجمے اور تخلیق میں کچھ فرق نہ ہو، مناسب نہیں۔ہزار کوشش وکاوش کے باوجود ترجمہ، ترجمہ ہی رہتا ہے اور وہ کسی طرح تخلیق کی برابری نہیں کر سکتا۔اس حقیقت کے باوصف ترجمے کی قدروقیمت کم نہیں ہوتی۔ ترجمہ انتقالِ معنی کا فن ہے اور تخلیق کی طرح اس کی بھی ایک قائم بالذات حیثیت ہے جس کی قدروقیمت اور اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ دُنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے کی باقاعدہ اور منظم روایتیں اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کی گواہی پیش کرتی ہیں۔ ترجمہ مختلف قوموں، ملتوں ، تہذیبوں اور ثقافتوں کے مابین ایک پُل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ترجمے ہی کی وساطت سے ایک زبان کا فکری اور علمی سرمایہ بلکہ اظہار وبیان کے قرینے ، اسالیب کی خوش سیرتی اور تکنیکی زاویے دوسری زبانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ترجمے کے بارے میں ایک روایتی نقطۂ نظر یہ ہے کہ ترجمہ عورت کے مماثل ہے۔اگر یہ خوب صورت اور خوش شکل ہوتووفادار نہیں ہوتی اور اگر وفا شعار ہو تو خوب صورتی سے عاری ہوتی ہے۔یہ نقطۂ نظر جزوی صداقت کا حامل ہونے کے باوجود درست خیال نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ دُنیا کی مختلف زبانوں میں ایسے تراجم بھی موجود ہیں جن میں خوب صورتی اور وفا شعاری دونوں باہم گلے ملتی دکھائی دیتی ہیں۔
ترجمہ کارِ سہل نہیں بلکہ انتہائی دشوار گزار ، کٹھن اور کانٹوں بھرے راستوں سے گزرنے کا عمل ہے۔منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لیے مترجم کو طرح طرح کے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں اور حدود وقیود کی تنگنائے اور قدغنوں کے آہنی حصار میں ترجمے کے تنِ نازک کو محفوظ ومامون رکھنا پڑتا ہے۔ ترجمہ محض دو زبانوں کے الفاظ کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ ایک زبان کے تاریخی، تہذیبی، فکری اور لسانی پس منظر کوجمالیاتی رنگوں کے ساتھ دوسری زبان کے قالب میں ڈھالنے کا عمل ہے۔ ہر زبان اپنا الگ تہذیبی ، ثقافتی او رلسانی پس منظر رکھتی ہے،اس پس منظر سے کامل آگہی کے بغیر مترجم کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا۔ علومِ ترجمہ کی ماہر سوزن بیسنٹ(Susan Bassnett ) ایک مثال کے ذریعے مترجم کے وظائف بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
’’ ثقافت کے جسم کا دل زبان ہے اور ان دونوں کے باہمی تعامل سے زندگی بخش توانائی کا تسلسل پیدا ہوتا ہے۔اسی طرح جیسے دل کا اپریشن کرتے وقت کوئی سرجن مریض کے باقی جسم کو نظر انداز نہیں کر سکتا ۔کسی متن کو ترجمہ کرتے ہوئے کوئی مترجم اگر اس کے ثقافتی پس منظر کو نظر انداز کرے گا تو گھاٹے میں رہے گا۔‘‘(۱)
تخلیق کی تہذیب سے مترجم کسی طور صرفِ نظر نہیں کر سکتا۔اسے اپنے ترجمے میں بنیادی زبان کے تہذیبی رنگوں اور سماجی نقوش کو بھی منتقل کرناہوتا ہے اور اگر وہ اس پہلو کو نظر انداز کر دے تو محض الفاظ کے انتقال سے ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور یہ ساری کدوکاوش بے معنی سرگرمی بن کر رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کے بہ قول:
’’ ایک تہذیب کے تصورات دوسری تہذیب کے پیکر میں ڈھالنے ہوتے ہیں،اصل میں مترجم کا کام ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا نہیں ہے،ایک تہذیبی معنویت کو دوسری تہذیبی معنویت میں ڈھالنا ہے۔‘‘(۲)
ترجمے کی تاریخ میں ہمیں ترجمہ کاری کے مختلف طریقے اور اسالیب دکھائی دیتے ہیں۔ اوّل اوّل بنیادی زبان کے متن کو پڑھ کر اس کا اپنی زبان میں خلاصہ کر دینا یا متن کا لبِ لباب پیش کر دینا ترجمہ کہلایا۔اسے بعض اصحابِ نظر نے’’ آزاد ترجمہ‘‘کا نام دیا۔ اس طرز کے تراجم کا دُنیا بھر کی مختلف زبانوں میں چلن رہا۔ خود اُردو میں انیسویں صدی کے ربعِ آخر سے بیسویں صدی کے نصفِ اوّل تک اس طرز کے بے شمار ترجمے سامنے آئے۔افادیت کے باوجود اس طرح کے ترجمے کو ترجمہ کہنا مشکل ہے اور بہ قول شمس الرحمٰن فاروقیTrans-creationاورآزادترجمہ جیسی اصطلاحیں خراب ترجموں کا پردہ ہیں یا پھر ایسے تراجم کی حمایت کرتی ہیں جو اصل سے بہتر ہونے کی کوشش کرتےہیںیا اس کی توہین کرتے ہیں۔(۳)یہی صورتِ حال ’’ماخوذ ‘‘ پر بھی صادق آتی ہے کیوں اس عمل میں بھی کسی تخلیق کا مرکزی نکتہ یا بنیادی خیال لے کر اپنی زبان میں ایک نئی عمارت استوار کی جاتی ہے۔ ترجمے کا مقبولِ عام طریقہ لفظی ترجمہ ہے۔ یہ عمل ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے الفاظ میں ڈھالنے سے عبارت ہے۔ عام ہنری اور سائنسی ، علمی اور صحافتی متنوں کے دوسری زبانوں میں انتقال کے لیے یہ طریق بڑی حد تک معاون ہے۔ تاہم تخلیقی اور ادبی متون کو دوسری زبان کے قالب میں منتقل کرنے کے لیے ترجمے کے یہ طریق کسی طرح مناسب نہیں۔تخلیقی اور ادبی متون کے لیے ترجمہ بھی تخلیقی شان کا حامل ہونا چاہیے۔ڈاکٹر جمیل جالبی ترجمے مختلف طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’ ترجمے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اصل متن کا صرف لفظی ترجمہ کر دیا جائے اور بس۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مفہوم لے کر آزادی کے ساتھ اپنی زبان کے روایتی و مقبول اندازِ بیان کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیا جائے۔تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ترجمہ اس طور پر کیا جائے کہ اس میں مصنف کے لہجے کی کھنک بھی باقی رہے،اپنی زبان کا مزاج بھی باقی رہے اور ترجمہ اصل متن کے بالکل مطابق ہو۔ترجمہ کی یہ شکل سب سے زیادہ مشکل ہے۔ایسے ترجموں سے زبان وبیان کا ایک فائدہ تو یہ پہنچتا ہے کہ زبان کے ہاتھ بیان کا ایک نیا سانچہ آ جاتا ہے۔دوسرے ،جملوں کی ساخت ایک نئی شکل اختیار کر کے اپنی زبان کے اظہار کے سانچوں کو وسیع تر کر دیتی ہے۔‘‘(۴)
ترجمہ جوکھم کا معاملہ ہے ۔ عام علمی یا سائنسی متون کا ترجمہ بھی اگرچہ ریاضت کا متقاضی ہے مگر دونوں زبانوں کی لغت آشنائی اور مضمون سے ذہنی وابستگی اس کام کو نسبتاً آسان بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ادبی تخلیقات کا ترجمہ خواہ نثر میں ہو یا نظم میں،بے حد مشکل ہے۔ لفظ کا لفظ میں ترجمہ کرنے سے یہاں کام نہیں چلتا۔ لفظ کی اپنی کائنات ہوتی ہے اور صحیح طور پر کوئی دوسرا لفظ اس کی مکمل ترجمانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔اس کی محاکاتی فضا کو دوسری زبان کے قریب ترین مماثل لفظ کے ذریعے پیش کرنا نہایت دشوار ہے۔ منظوم ترجمے میں قیود اور قدغنیں بڑھ جاتی ہیں اور خیال کی کامل ترسیل کا عمل مزید سُست ہو جاتا ہے ۔یہی وجہ ہے دُنیا کے دانش وروں اور تخلیق کاروں کے خیال کے مطابق شاعری کو ترجمے کے عمل سے نہیں گزارا جا سکتا۔وکٹر ہیوگو نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نظم کے ترجمے کا خیال ہی بے معنی اور ناممکن ہے۔ ڈاکٹر جانسن نے بھی شاعری کے ترجمے کو کارِ فضول قرار دیا ہے مگر اس کے باوجود مشرق ومغرب میں شاعری کے منظوم تراجم کی باقاعدہ روایات موجود ہیں اور بڑے بڑے شعراکا شعری سرمایہ ایک زبان سے دوسری زبانوں میں منتقل ہوا ہے۔ منظوم ترجمے کے لیے مترجم کا اچھا شاعر ہونا تو شرطِ اوّل ہے؛دوسری شرائط میں مترجم کی دونوں زبانوں پر قدرت ،دونوں زبانوں کے لسانی مزاجوں سے کامل آشنائی اور دونوں زبانوں کے ادبیات کے ایک بڑے حصے سے واقفیت شامل ہیں۔ہر زبان اپنے مخصوص اوزان وبحور ، استعارات وعلامات اور رموز واشارات رکھتی ہے۔مترجم کی ان سے ناواقفیت ترجمے کے عمل کو پنپنے نہیں دیتی۔ منظوم ترجمے کا سب سے مقدم تقاضا یہ ہے کہ مترجمٰ محض شعرکہنے کی صلاحیت سے متصف نہ ہو بلکہ شعر فہمی کا اعلیٰ ذوق بھی رکھتا ہو۔منظوم ترجمہ کار کے لیے شاعر کے فلسفۂ حیات، طرزِ احساس، علمی لیاقت ، نفسیاتی کیفیت اور اس کے فنی طریقۂ کار کا جاننا نہایت بنیادی ضرورت ہے۔کیوں کہ ہر تخلیق کار موضوع اور تکنیکی عناصر کو اپنے طور پر برتنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے مترجم پر لازم ہے کہ وہ اس کے الفاظ، تراکیب، محاورات، استعارات وتشبیہات، پیکروں ، علامتوں اور اساطیر کو تخلیق کار کے فکر وفن اور اس کے مخصوص انداز واسلوب کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر ترجمہ کرتے وقت محض کسی ایک فن پارے کو سامنے رکھنے اور شاعر کے باقی شعری سرمائے سے ناواقف ہونے کے باعث منظوم ترجمہ درست صورت میں نہیں ڈھل سکتا۔منظوم ترجمے کی مشکلات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے منظوم ترجمہ کاروں کوظ۔انصاری انتباہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’ جو شخص خود اچھا شعر نہ کہہ سکے،نہ کہہ چُکا ہو،جسے اپنی زبان میں اساتذہ کے ہزاروں اشعار ازبر نہ ہوں،جو دوسری زبان کے مصرعوں میں، نظموں میں (بلکہ نثر میں بھی) باطنی آہنگ اور ظاہری ترنم سے لطف اندوز نہ ہو سکے،اسے منظوم ترجمے کی اوکھلی میں سر نہ دینا چاہیے۔‘‘(۵)
شاعری کا ترجمہ شاعری کے علاوہ نثر میں بھی کیا جاتا ہے اور دُنیا کی مختلف زبانوں میں شاعری کے منثور ترجمے کی باقاعدہ روایتیں موجود ہیں۔ ان منثور تراجم سے کسی حد تک شاعر کے موضوعات اور اس کے فکر کی مختلف صورتوں کو تو سمجھا جا سکتا ہے مگر اس کی شاعرانہ شخصیت ترجمے کے نثری قالب میں پوری طرح نہیں ڈھل سکتی۔اسی لیے بعض اصحابِ علم کے نزدیک شاعری کا ترجمہ شاعری ہی میں ہونا چاہیے تاکہ نغمے کا جادو اور روحانی کیف بھی کسی طرح ترجمے میں شامل ہو کر شاعر کے کلام کے غنائی اور وجدانی عناصر کی تفہیم میں مددگار ہو۔ اُردو کے معروف مترجم،شاعر اور زبان دان شان الحق حقی اس ضمن میں اپناخیال یوں پیش کرتے ہیں:
’’شعر کی روح شعر ہی میں سما سکتی ہے۔اس کے لیے نغمے کا وہ جادو، آہنگ کی لطیف ضرب اور جمال وکمال کا وہ کرشمہ ضروری ہے جس کے بغیر وہ صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتیں جو وجدانی حقائق کا ادراک کر سکیں۔نظم کا ترجمہ نثر میں نحویوں اور لسانیوں کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے مگر روحانی اکتساب کی راہ نہیں پیدا کرتا۔‘‘(۶)
شعری ترجمے کے لیے مترجم کو کانٹوں بھرے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے صحیح معنوں میں دُہری مشقت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شعری متن کے جملہ اوصاف سے کامل آگاہی کے بعد ایک طویل مدت تک اس فضا میں سفر کر کے شاعر کے ہم قدم ہونے تک کا مرحلہ جس قدر دشوار اور کٹھن ہے ، اسے اپنی زبان کے قالب میں ڈھالنے کا عمل اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔مترجم کودو زبانوں کی شعری روایتوں کا بارِ گراں اُٹھا کراس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے۔سیّد عبداللہ مترجم کے اس مشکل سفر کی بابت رقم طراز ہیں:
’’ تخلیق کارِ اوّل(شاعر) اپنا ہی بوجھ اُٹھاتا ہے وہاں بچارے مترجم کو تخلیق کار کے بوجھ کے ساتھ اپنا بوجھ بھی اُٹھانا پڑتا ہے۔اس کی ذمہ داری، تخلیقِ اوّل کو نئے باطن میں لے جا کر اس کی مربیانہ پرداخت کی بھی ضرورت ہوتی ہے،جس کے دوران اس کو تخلیق کار کے جملہ تجربات کو اپنے تجربات کے اندر جذب کر لینا پڑتا ہے۔اس مقام پر پہنچ کر وہ بھی تخلیق کار بن جاتا ہے مگر ایسا تخلیق کار جس کے سر پر ہر وقت ’’منتِ غیر‘‘ کی تلوار بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔‘‘(۷)
دُنیا کی مختلف زبانوں نے قریبی اور ہمسایہ زبانوں کے علاوہ دوسری عالمی زبانوں کی منتخب شاعری کو ترجمہ کر کے زبان وبیان کے نئے اسالیب اور فکر وفن کے جدید زاویوں سے اپنے ادبیات کو ثروت مند کیا ہے۔ ایک ہی لسانی کنبے سے تعلق رکھنے والی زبانوں میں ترجمے کا عمل قدرے بہتراور نسبتاً سہل ہوتا ہے۔مشرقی زبانوں میں تہذیبی اور لسانی سانجھ کے باعث باہمی تراجم کا سفر زیادہ پیچیدہ اور دشوار گزار نہیں۔ اس کے باوجود لفظیات، بحر، بندش،ہیئت اور دوسرے فنی لوازمات کوملحوظ رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا جوکھم کا معاملہ ہے۔ مترجمین کو ترجمہ کی تنگنائے سے گزرتے وقت جن جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اورترجمے کے دوران وہ جن مسائل سے نبرد آزما رہتے ہیں،مشرقی زبانوں کے باہمی تراجم کی روشنی میں ان کا اجمالی ذکرذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔
مشرقی زبانوں میں ایسے تراجم عام ہیں جن میں دونوں زبانوں کی شعری روایت سے مترجم نے صرفِ نظر کیا ہے ۔مترجم چوں کہ خود شاعر ہے اس لیے اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی شاعرانہ شخصیت کو تخلیق کار کی شاعرانہ شخصیت سے آمیز نہ کرے۔اگر مترجم اچھا شاعر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ تخلیق سے بہتر قرار پائے اور اگر وہ خود اچھا شاعرنہیں تو تخلیق کے حسن کو ترجمے میں ڈھالنے سے قاصر وعاجز ہو گا۔ دونوں صورتوں میں ترجمے کو معیاری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تخلیق کار سے کئی قدم آگے نکل جانا یا اس سے بہت پیچھے رہ جانا مترجم کی حیثیت کو مشکوک بنادیتاہے۔شاعری کا ترجمہ کرتے وقت مترجم کو تخلیق کار کے عہد کا بھی راز داں ہونا چاہیے۔تخلیق کار کا اسلوب اور انداز انفرادی اور ذاتی ہوتے ہوئے بھی اپنے عصر اور زمانے سے پیوستہ ہوتا ہے ۔ تخلیق کار اپنے عصر کے معاشی، سماجی، تہذیبی، سیاسی ، ادبی اور علمی تصورات سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔اس کی تخلیق روحِ عصر سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہوتی ہے اس لیے مترجم اگر تخلیق کار کے عہد کی روایات، تحریکات ، اقدار اور سماجی پس منظر سے واقف نہیں ہو گا تو اس کاترجمہ معیاری ترجمے کی صف میں کبھی شامل نہیں ہو سکے گا۔ حافظ، رومی ، خیام اور سعدی کے کلام کے اُردو منظوم تراجم میں بیش تر تراجم ایسے ہیں جن میں مترجم کی نظر محض زیرِ ترجمہ تخلیق تک رہی یوں ترجمہ خام رہ گیا ۔
اچھاشعر کاروانِ معانی کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔شعر کا یہ وصف مترجم کے لیے کئی مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ کون سا مفہوم تخلیق کار کی منشا کے مطابق ہے ، اس کا فیصلہ کرناآسان نہیں ہوتا۔ تاہم اعلیٰ درجے کی شعر فہمی اور تخلیق کار کے ذہنی، فکری اور شعری زاویوں سے واقفیت اس مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ مترجم انتشارِ معنی سے دامن بچا کرکسی ایک معنی کا انتخاب کر کے اس مسئلے سے وقتی طور پر نکل آتا ہے مگر اس کا امتحان ختم نہیں ہوتا۔اس سے بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے جو مترجم کے قدم روک لیتی ہے وہ تخلیق کار کا بین السطور یا ماورائے سطور تصور ہے جو لفظوں میں نہیں ڈھلتا مگر مسلسل لَو دیتا ہے۔ مترجم کو اس نوع کے مقامات سے گزرتے وقت واقعی دانتوں پر پسینا آ جاتا ہے۔ تخلیق کار کا ابہام اور اس کی ایمائیت اگر ترجمے میں وضاحت اور تفصیل بن جائے تو ترجمے کا حسن گہنا جاتا ہے ۔اس مسئلے کے ساتھ تخلیق تجربے کا اسلوب،فن پارے کی داخلی تنظیم ، زبان کے ظاہری عناصر، فن کی لوازمے کے ساتھ پیوستگی نئے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ڈاکٹر عنوان چشتی کے بہ قول:
’’لفظی ترجمے میں لغت کی مدد سے لفظوں یا جملوں اور اقتباسوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔یہ صورتِ حال نثر میں تو کسی حد تک گوارا ہو سکتی ہے مگر نظموں کے منظوم تراجم میں ناکام ہو جاتی ہے۔شاعری میں الفاظ، استعارات، پیکروں اور علامتوں کے مجازی اور تخلیقی معانی ہوتے ہیں،اس لیے محض معنی لکھنے سے شاعر کے اصل خیال کی عکاسی نہیں ہو سکتی۔‘‘(۸)
فارسی سے متأثر جنوبی ایشیا کی مسلم زبانوں اورخاص طور پر پاکستانی زبانوں میں لسانی اور تہذیبی سانجھ کے باعث منظوم ترجمے کا عمل نسبتاً کم مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خوشحال خان خٹک ، شاہ عبداللطیف بھٹائی، مست توکلی، بلھے شاہ، بابا فرید، سلطان باہو ، شاہ حسین اور دوسرے پاکستانی زبانوں کے شاعروں کے منظوم باہمی تراجم میں ان مسائل کا عمل دخل کم کم ہے لیکن انھی شعرا کے انگریزی اور دوسری عالمی زبانوں میں منظوم تراجم میں یہ مسائل سر اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں۔معروف شاعر اور مترجم شان الحق حقی رقم طراز ہیں:
’’تراجم کے ذریعے اچھے ادب کا تبادلہ سب سے زیادہ اطمینان بخش طور پر ہماری پاکستانی زبانوں کے درمیان ہو سکتا ہے جو آپس میں ہم رشتہ ہیں اور مشترک لغات ومحاورات وامثال کے علاوہ ترکیبِ نحوی بھی بڑی حد تک مماثل یا مشترک ہے۔‘‘(۹)
اُردو کی تعمیر وتشکیل میں مختلف زبانوں نے اپنا حصّہ ڈالاہے۔ ان زبانوں میں فارسی کا حصہ نسبتاً سب سے زیادہ ہے۔یہی سبب ہے کہ فارسی اور اُردو کے باہمی تراجم میں تخلیق اور ترجمے کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا اور اچھے مترجم اُردو فارسی کے قریبی تعلق کے باعث تخلیق اور ترجمہ میں بھی قُرب کی فضا خلق کرتے ہیں۔ دونوں زبانوں کے مشترک ذخیرۂ لفظیات ، تراکیب وتشبیہات اور اوزان وبحور کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مترجم ترجمہ میں تخلیق جیسے اوصاف پیدا کر کے ترجمہ کو کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے۔فارسی سے اُردو میں ہونے والے ایسے منظوم تراجم سے ایک دو مثالیں مشتے نمونہ از خروارے پیش کی جاتی ہیں :
اقبال:
مئےِ دیرینہ و معشوقِ جواں چیزے نیست پیشِ صاحب نظراں حورِ جناں چیزے نیست ہر چہ از محکم و پایندہ شناسی ، گذرد کوہ و صحرا و بر و بحر و کراں چیزے نیست دانشِ مغربیاں ، فلسفۂ مشرقیاں ہمہ بت خانہ و در طوفِ بتاں چیزے نیست(۱۰) |
رفیق خاور:
مئے دیرینہ و معشوقِ جواں کچھ بھی نہیں پیشِ اربابِ نظر حور و جناں کُچھ بھی نہیں جس کو پائندہ سمجھتے ہیں وہ پائندہ کہاں کوہ و صحرا و بر و بحر و کراں کچھ بھی نہیں دانش و حکمتِ مغرب ہو کہ فکرِ مشرق دونوں بُت خانے ہیں اور طوفِ بتاں کچھ بھی نہیں(۱۱) |
تین اشعارکے اس ترجمے میں مئے دیرینہ، معشوقِ جواں،حور وجناں، پائندہ، پیش، کوہ، صحرا، بر، بحر، کراں،دانش، بت خانہ اورطوفِ بتاں جیسے الفاظ وتراکیب مشترک ہیں۔ اس اشتراکِ تخلیق وترجمہ کے باعث ترجمہ کا معیار بلند ٹھہرا اور فکرِ شاعر کامیابی کے ساتھ لباسِ ترجمہ میں ڈھلی۔
اقبال:
ناموسِ ازل را تو امینی تو امینی دارائے جہاں را تو یساری تو یمینی اے بندۂ خاکی تو زمانی تو زمینی صہبائے یقیں در کش و از دیرِ گماں خیز از خوابِ گراں ، خوابِ گراں ، خوابِ گراں خیز از خوابِ گراں خیز! (۱۲) |
عبدالعلیم صدیقی:
ناموسِ ازل کی تجھے سونپی ہے امینی دارائے جہاں کا تو یساری تو یمینی اے بندۂ خاکی تو زمانی تو زمینی صہبائے یقیں نوش کر ، اُٹھ دیرِ گماں سے اُٹھ خوابِ گراں ، خوابِ گراں ، خوابِ گراں سے اُٹھ خوابِ گراں سے(۱۳) |
اس بند کا ترجمہ کرتے ہوئے عبدالعلیم صدیقی نے تخلیق کے بیشتر الفاظ وتراکیب ہو بہ ہو اپنے ترجمے میں شامل کر لیے ہیں۔ اس استفادے کے باعث ترجمے کے پیکر میں تخلیق کا جلال و شکوہ اور مزاج وکیف بھی گھل مل گیا ہے۔
اُردو اور پنجابی کی لسانی قربت بھی دونوں زبانوں کے باہمی ترجمے میں اپنا جادو جگاتی ہے۔مترجمین نے ان زبانوں کے تعلق کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ایسے کامیاب اور عمدہ ترجمے کیے ہیں جو تخلیق کے ہم سر اور برابر دکھائے دیتے ہیں۔مرزا اسد اللہ خاں غالبؔ جیسے مشکل شاعر کے کلام کو پنجابی کے قالب میں ڈھالتے ہوئے معروف مترجم اسیر عابد کو جن کٹھن راستوں سے گزرنا پڑا، اس کا صحیح اندازہ تو خود انھی کو ہو گا مگر دونوں زبانوں پر قدرت رکھنے اور دونوں زبانوں کے مزاج سے آشنائی کے باعث غالبؔ کا ایسا اعلا ترجمہ کرنے میں وہ کام گار ہوئے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی نے اسے’’ ترجمے کا معجزہ‘‘ قرار دیاہے۔ دیوانِ غالب ؔ کے پنجابی ترجمے سے دو تین مثالیں دیکھیے:
غالبؔ :
کوئی دن گر زندگانی اور ہے اپنے جی ہم نے میں ٹھانی اور ہے آتشِ دوزخ میں یہ گرمی کہاں سوزِ غم ہائے نہانی اور ہے(۱۴) |
اسیر عابد:
چار دہاڑے جے کر اَجے حیاتی ہور اے میں وی اپنے دل اندر ہُن دھاری ہور اے دوزخ دے انگیارے ایڈے ساڑو کِتھوں گھجیاں پِیڑاں سینے دُھونی دھُخد ہور اے(۱۵) |
غالبؔ :
بازیچۂ اطفال ہے ، دُنیا، مرے آگے ہوتا ہے شب و روز ، تماشا مرے آگے اِک کھیل ہے ، اورنگِ سلیماں ، مرے نزدیک اِک بات ہے ، اعجازِ مسیحا ، مرے آگے(۱۶) |
اسیر عابد:
کھیڈ ایانے بالاں ورگی دُنیا میرے اگے اَٹھے پہر تماشا ہُندا رہندا میرے اگے کھیڈ نری اے تخت سلیمانی دی میرے کیتے گل نری اے ، جو کردے سَن عیسیٰ میرے اَگے(۱۷) |
منظوم ترجمے میں ہیئت، بحر، قافیہ اور ردیف کے التزام کے باعث بھی کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ مشرقی زبانوں کے باہمی تراجم میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں جن کے ذریعے ان مسائل کی نشان دہی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر حکیم عمر خیام کے کئی منظوم تراجم اُردو اور پاکستان کی دوسری زبانوں میں ہوئے ہیں۔ بعض مترجمین نے رباعی کا ترجمہ رباعی کی شکل میں پیش کرکے اپنے مسائل میں اضافہ کیا ہے۔جن مترجمین نے قطعے کی ہیئت اختیار کی وہ فکر کی مؤثر ترسیل میں زیادہ بامراد ٹھہرے۔ ترجمہ کرتے وقت تخلیق کارکے فکرکی مؤثر ترسیل کے ساتھ ساتھ فنی اور تکنیکی لوازمات کا بارِ گراں اٹھانا مشکل کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہیئت کی سختی اور غلط ہیئت کا چناؤ مسائل کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ چودھری شہاب الدین نے مسدسِ حالی کے پنجابی ترجمے کے لیے مثلث کی ہیئت اختیار کی۔ انھیں چند بند کرنے کے بعد ہی اس مشکل کا اندازہ ہو گیا مگر وہ جوں توں کر کے ترجمہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چھے مصرعوں کا ترجمہ تین مصرعوں کے پیکر میں ڈھالنا کس قدر مشکل ہے،اس کا اندازہ ان کا ترجمہ دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے مسدس کی ہیئت ہی انتخاب کرتے تو ممکن ہے ترجمے کا معیار مزید بہتر ہو جاتا۔اس التزام سے اگرچہ انھیں بہت مشکل پیش آئی تاہم اُن کا ترجمہ معیار کے اعتبار سے بلند مرتبہ رکھتا ہے اور انھوں نے کامیابی کے ساتھ مسدس کو مثلث کے قالب میں ڈھالا ہے۔ ایک بند بہ طور مثال دیکھیے:
مولاناحالیؔ :
وہ دُنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بِنا کا ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے اُبلے گا چشمہ ہدیٰ کا وہ تیرتھ تھا اِک بُت پرستوں کا گویا جہاں نامِ حق کا نہ تھا کوئی جویا(۱۸) |
چودھری شہاب الدین:
پہلا رب دا تھاں اوہ وچ دُنیا، جیہنوں آپ خلیل بنایا سی سوُہتا نور دا کڈھنا سی اوتھوں ، دھروں رب نے پک پکایا سی تیرتھ اوہ سی بُت پجاریاں دا ،نیڑے رب دا نام نہ آیاسی(۱۹) |
مشرقی زبانوں کے ا چھے منظوم تراجم میں ترجمہ وتخلیق ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے نظر آتے ہیں۔ایسے تراجم کو تخلیقی ترجمہ کا درجہ حاصل ہے ۔یہ درجہ انھی تراجم کا مقسوم بنتا ہے جن کے مترجم اعلا تخلیقی اور ادبی اوصاف سے مالا مال ہوتے ہیں اور تخلیق کے باطن میں اُترنے اور اسے تمام تر رنگوں کے ساتھ اپنی زبان کے قالب میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ السنۂ شرقیہ میں باہمی منظوم ترجمے کی ایک مستحکم روایت موجود ہے اور اس روایت میں تخلیقی شان کے وہ منظوم تراجم موجود ہیں جن سے ترجمے کا اعتبار قائم ہے ۔
حوالہ جات
۱۔ علومِ ترجمہ( مترجم: توحید احمد)؛ گجرات؛ شعبۂ تصنیف وتالیف،گجرات یونی ورسٹی؛ جولائی،۲۰۱۵ء؛ ص۴۰۔
۲۔ ’’ترجمہ: نوعیت اور مقصد‘‘ مشمولہ: ترجمہ کا فن اور روایات( مرتبہ: ڈاکٹر قمر رئیس)؛ دہلی؛ تاج پبلشنگ ہاؤس؛ ۱۹۷۹ء؛ ص ۷۱،۷۲۔
۳۔ ’’دریافت اور بازیافت‘‘ مشمولہ: فنِ ترجمہ کاری(مرتب: صفدر رشید)؛ اسلام آباد؛ پورب اکادمی؛ مارچ،۲۰۱۵ء؛ ص ۳۸۔
۴۔ ’’ترجمے کے مسائل‘‘؛ مشمولہ: ترجمہ: روایت اور فن(مرتبہ: نثار احمد قریشی)؛ اسلام آباد؛ مقتدرہ قومی زبان؛ ۱۹۸۵ء؛ ص ۱۵۵،۱۵۶۔
۵۔ ’’ترجمے کے بنیادی مسائل‘‘ مشمولہ:ترجمہ کا فن اور روایات( مرتبہ: ڈاکٹر قمر رئیس)؛ دہلی؛ ص ۱۹۹۔
۶۔ ’’ مقدمہ‘‘ مشمولہ: خیابانِ پاک؛ کراچی ،ادارۂ مطبوعاتِ پاکستان؛۱۹۵۶ء؛ ص ہ۔
۷۔ ’’پیش لفظ‘‘ مشمولہ: جاوید نامہ(مترجم : رفیق خاور)؛ لاہور؛اقبال اکادمی، پاکستان؛ ۱۹۷۶ء ؛ ص م۔
۸۔ ’’منظوم ترجمے کا عمل‘‘: مشمولہ: ترجمہ کا فن اور روایات؛ص۱۵۱۔
۹۔ ’’ادبی تراجم کے مسائل‘‘ مشمولہ:فنِ ترجمہ کاری: ص۲۵۸۔
۱۰۔ جاوید نامہ: لاہور؛ شیخ غلام علی اینڈ سنز؛ طبعِ ششم، دسمبر۱۹۶۶ء؛ ص ۴۸۔
۱۱۔ جاوید نامہ(مترجم: رفیق خاور)؛ ص۳۷۔
۱۲۔ زبورِ عجم مشمولہ: کلیاتِ اقبال فارسی؛ لاہور؛ شیخ غلام علی اینڈ سنز؛ س ن۔ ص ۴۷۳۔
۱۳۔ نغمۂ سروش؛ لاہور؛ مقبول اکیڈمی؛ ۲۰۰۰ء؛ ص ۷۷۔
۱۴۔ دیوانِ غالب ؔ کامل؛(مرتبہ: کالی داس گپتا رضا)؛ کراچی؛ انجمن ترقیِ اُردو پاکستان؛ سو،۔ ۹۷-۱۹۹۶ء؛ ص ۲۹۴۔
۱۵۔ دیوانِ غالب(منظوم پنجابی ترجمہ: اسیر عابد)؛ لاہور؛ مجلسِ ترقیِ ادب؛ مئی ۱۹۸۷ء؛ ص۲۹۷۔
۱۶۔ دیوانِ غالب کامل: ص ۳۲۵،۳۲۶۔
۱۷۔ دیوانِ غالب(منظوم پنجابی ترجمہ: اسیر عابد)؛ ص۳۹۱۔
۱۸۔ مسدسِ حالی؛ لاہور؛ تاج کمپنی لمیٹڈ؛ س ن ؛ ص ۱۲۔
۱۹۔ مسدسِ حالی دا پنجابی ترجمہ:لاہور؛ عطر چند کپور؛ ۱۹۳۱ء؛ ص۹۔